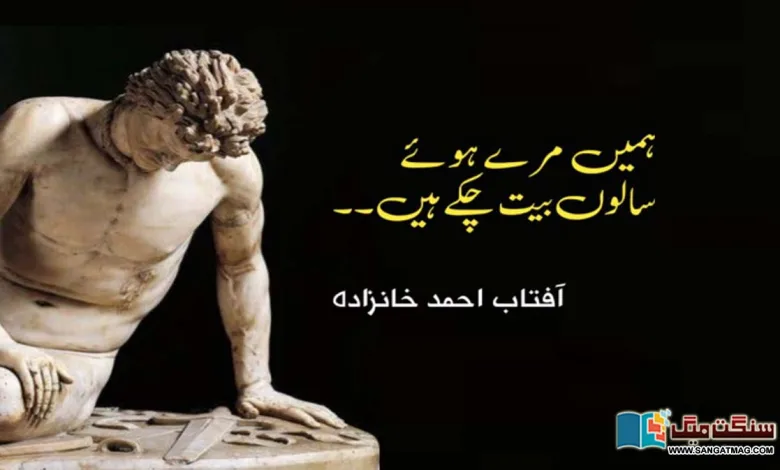
1957میں نوبیل انعام کے لیے دو لکھنے والوں کے درمیان ووٹ ڈالے گئے، البر کامیو نے ایک ووٹ زیادہ حاصل کیا اور نوبیل انعام کا حق دار قرار پایا، ایک ووٹ سے شکست کھانے والا یونان کا جدید مصنف کازان زاکیز تھا انعام لیتے وقت کا میو نے کہا ’’انعام تو مجھے مل گیا ہے لیکن کازان زاکیز اس انعام کا مجھ سے سو گنا زیادہ حقدار ہے۔‘‘
ہومر سے عمر میں تقریباً پونے دو ہزار سال چھوٹا کازان زاکیز، سمجھ لیں دوسرا جدید ہومر تھا یا یوں کہہ لیں کہ قدیم ہومر سے کچھ لکھنے کا کام باقی رہ گیا تھا، چنانچہ وہ کازان زاکیز کے روپ میں دوبارہ پیدا ہوا اور جدید یونانی زبان میں شاہکار لکھ ڈالے۔ کازان زاکیز کی قبر کے کتبے پر درج ہے ’’اب مجھے کوئی خوف نہیں، کوئی خواہش نہیں، اب میں آزاد ہوں۔‘‘ ظاہر ہے یہ تحریر کازان زاکیز کی خواہش پر لکھی گئی ہوگی۔
کازان اس سچ سے بخوبی واقف تھا کہ انسان اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتا، جب تک وہ خوف اور خواہش پر قابو نہ پا لے، اسے تسخیر نہ کر لے۔ خوف خواہش کو جنم دیتا ہے اور خواہش خوف کو جنم دیتی ہے یعنی آپ اگر ان دونوں میں سے ایک کو دبوچ لیتے ہیں تو دوسرا خود بخود مرجاتا ہے، پھر آپ آزاد ہو جاتے ہیں، پھر آپ کو کوئی چیز قید نہیں کر سکتی، اپنی حراست میں نہیں لے سکتی۔
یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ایسا کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ عقل وخرد وہ واحد چیز ہے جو آپ کو آزاد کروا دیتی ہے۔ جب گوتھس نے روم کو تاخت و تاراج کیا تو روم ایک تنگ و تاریک گاؤں میں تبدیل ہو گیا۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہاں کے لوگوں نے مایوس ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے، خوف کے مارے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا تھا۔
انگلینڈ میں انیسویں صدی میں معاشی استحصال، سیاسی جبر، ناانصافیوں اور مظالم کی تصاویر ہمیں اس دور کے ادیبوں کی تحریروں میں ملتی ہیں۔ ایلیٹ ایک پسماندہ اور ذلتوں کے مارے خاندان کی منظر کشی کرتے ہوئے کہتا ہے ’’جب خاندان ذلت کی گہرائیوں میں گر گیا تو اپنی جائیداد اونے پونے داموں نیلام کرنا پڑی، باپ مایوسی کی حالت میں نشے کا عادی ہو گیا اور ماں نے غصے اور ذہنی انتشار کا شکار ہو کر اپنے بیٹے کو مار ڈالا، بہن غربت اور مایوسی سے تنگ آ کر اپنی عصمت بیچنے پر مجبور ہو گئی۔‘‘
اس نظم کا اختتام ان سطروں پر ہوتا ہے: ’’او خدایا! روٹی کس قدر مہنگی ہے اور خون کس قدر سستاہے۔۔‘‘
تھامس ہڈ نے 1844 میں ’شرٹ‘ پرایک نظم میں کہا کہ ’’جب تم مرغ کی اذان سنو تو کام، کام، کام۔۔ یہاں تک کہ تاروں کی لو تمہارے خون سے چمکنے لگے۔ جو لوگ اس شرٹ کو پہنتے ہیں، انھیں کیا معلوم کہ اس کی قیمت کتنی بھاری ہے‘‘
اسی طرح چارلس ڈکنز اور تھیکرے نے اپنے ناولوں میں پسے ہوئے طبقات کی نمایندگی کی۔ جب کہ بلزاک، زولا اور وکٹر ہیوگو نے اپنی تحریروں میں اس دور کے فرانس کی نقشہ کشی کی، گوگول، پشکن، ٹالسٹائی، چیخوف نے روس کے عام لوگوں کی زندگیوں کو اجاگر کیا۔
لوگ اور لوگوں کا ہجوم دو مختلف چیزیں ہیں۔ جب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے مقصد سے ہٹ جاتی ہے عقل و خرد، آگہی، فکر اور سوچ سے بیگانہ ہوجاتی ہے تو لوگوں کا یہ جمِ غفیر ایک ہجوم میں بدل جاتا ہے۔ مقصد کے بغیر لوگ ایک ایسا ہجوم بن جاتے ہیں، جن میں ہر ایک صرف اپنی ذات کے لیے زندہ رہتا ہے۔ اس کے سامنے صرف اور صرف ایک ہی مقصد باقی رہتا ہے کہ اپنی خواہشاتِ نفسانی کی تکمیل کس طرح کرنی ہے اور بس۔۔ لوگوں کا بے مقصد اور بے منزل ہجوم ہر وقت اپنی ہوس کی پوجا کا متمنی رہتا ہے۔ یہ ہجوم نا چاہتے ہوئے اس نظام کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو پہلے ہی مر چکا ہوتا ہے، وہ اپنی ساری توانائی اسے دوبارہ زندہ کرنے کے لے لگا رہا ہوتا ہے۔ وہ غربت، افلاس، بیماریاں، ذلتیں، غلاظتیں اپنا نصیب اور مقدر سمجھنے لگتا ہے اور ان ہی میں اسے تسکین ملتی ہے۔
آسکر وائلڈ کہتا ہے ’’المیہ ہے کہ کتنے ہی کم لوگ مرنے سے پہلے اپنی روح رکھتے ہیں۔ کسی بھی آدمی میں اس کے خود کے عمل سے زیادہ نایاب کوئی چیز نہیں ہے یہ سراسر سچ ہے زیادہ تر لوگ دوسرے لوگ ہیں‘‘
نطشے سے کسی نے پوچھا کہ ’’ہم اپنی شخصیت کو کیسے ترقی دے سکتے ہیں؟‘‘ نطشے نے عجیب بات کہی، ”خطرے میں جیو۔“ مگر ہم سوچتے ہیں کہ ہر لحاظ باحفاظت بنیں۔ اصل میں زندگی کے ہر لمحے کو جینا چاہیے۔ زندگی جینے کا صرف ایک مطلب ہے کہ خطرے میں رہو، اس طرح تمہاری شخصیت نکھرے گی، تم میں حوصلہ پیدا ہوگا۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہے ہی نہیں۔ مردہ اجسام کو دیکھو بالکل محفوظ ہیں، انھیں کوئی خطرہ نہیں۔ وہاں ان کی قبریں محفوظ ہیں کیونکہ وہ اب دوبارہ مر نہیں سکتے۔ موت کا آخری انعام مزید مرنے سے بچنا ہے، کیونکہ انہیں اب کوئی بھی دوبارہ مار نہیں سکتا۔
مشیل ہوئل بیک نے کہا تھا ’’یہ مستقبل نہیں بلکہ ماضی ہے، جو آپ کو مارتا ہے، اذیت دیتا ہے اور کمزور کرتا ہے اور موثر طریقے سے آپ کو مار کر ختم کردیتا ہے۔‘‘ ہم اگر یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم زندہ ہیں تو ہم سے زیادہ لاعلم کوئی اور نہیں، کیونکہ ہمیں مرے ہوئے سالوں بیت چکے ہیں۔۔ اب تو ہم صرف اس بات پر خوفزدہ ہیں کہ دوبارہ نہ جی اٹھیں۔ اگر ہم زندہ ہوتے تو سوچو، کیا اس حال میں جی رہے ہوتے، اس طرح ڈرے اور سہمے ہوئے ہوتے۔۔ اس طرح دنیا بھر کی تمام ذلتیں خوشی سے برداشت کررہے ہوتے!؟ ہم سب ماضی ہیں اور ماضی ہی کے ہاتھوں مارے گئے ہیں۔ اسی لیے تو پورے ملک میں خاموشی ہے پورا کا پورا ملک قبرستان بن گیا ہے، ہر طرف سناٹا ہی سناٹا ہے۔
روم کے کیپٹولین Capitoline عجائب گھر میں سنگ مرمر پر کی ہوئی سنگ تراشی کا ایک نمونہ رکھا ہوا ہے، جو ایک بہترین تخلیق ہے۔ یہ مجسمہ ہے ایک ’مرتے ہوئے گال‘ کا۔ (گال مغربی یورپ کے اس علاقے کا پرانا نام ہے، جو اب فرانس لکسمبرگ اور سوئٹزر لینڈ کا حصہ ہے۔ گال کے باشندے بھی گال ہی کہلاتے تھے۔) وہ شخص شدید زخمی میدان جنگ میں لیٹا ہوا ہے، لڑائی سے سخت کوش اس کا تنومند جسم موت کی آغوش میں جا رہا ہے۔ اس کا موٹے بالوں سے ڈھکا سر ڈھلکا ہوا ہے، اس کی مضبوط گردن مڑی ہوئی ہے۔ مزدوروں جیسے طاقت ور کھر دے ہاتھ جو ماضی قریب میں تلوار اٹھاتے تھے، اب زمین پر ٹیک لگا کر آخری کوشش سے اپنا ڈھلتا ہوا بدن سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسے ان خداؤں سے جنگ کرنے پر اکسایا گیا تھا، جنہیں وہ جانتا نہیں تھا۔ اپنے ملک سے بہت دور اور اس طرح وہ اپنے انجام کو پہنچا اب وہ اس مقام پر لیٹا ہوا خاموشی کی موت مر رہا ہے۔ دنگے فساد کی آوازیں اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی ہیں۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اندر کی جانب پھری ہوئی ہیں۔ وہ شاید آخری بار اپنے بچپنے کے گھر کو تک رہا تھا، جب جب ’مرتے ہوئے گال‘ کا مجسمہ یاد آتا ہے، تب تب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم سب ’مرتے ہوئے گال‘ کے مجسمے بن چکے ہیں اور اپنے بچپنے کے پاکستان کو تک رہے ہیں، اسے یاد کر رہے ہیں۔۔ جہاں ہم سب آزاد تھے، پُرسکون اور خوش تھے۔۔ جہاں سب پیٹ بھر کے روٹی کھاتے تھے، جہاں کوئی خوف نہیں تھا، ساری خواہشیں پوری ہو جاتی تھیں۔۔ فکر و سوچ پر کوئی پابندی نہیں تھی، جہاں لوگ ٹانگوں پر نہیں بلکہ اخلاقیات پر کھڑے تھے۔ جہاں انسانی المیوں کا کوئی وجود نہ تھا۔
بشکریہ ایکسپریس نیوز
(نوٹ: کسی بھی بلاگ، کالم یا تبصرے میں پیش کی گئی رائے مصنف/ مصنفہ/ تبصرہ نگار کی ذاتی رائے ہوتی ہے، جس سے سنگت میگ کا متفق ہونا ضروری نہیں۔)




