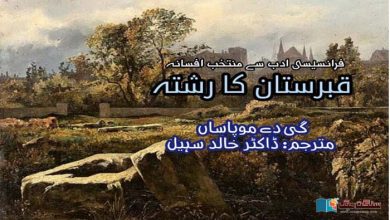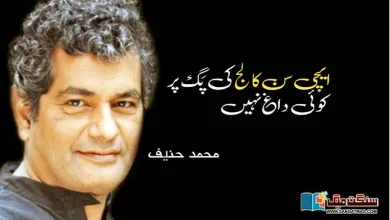پاکستان کے وسیع و عریض سندھ ڈیلٹا کے ایک چھوٹے سے ماہی گیری گاؤں داندو جیٹی میں ایک کشتی خالی کی جا رہی ہے، جبکہ دوسری سمندر کے لیے روانگی کے لیے تیار ہے۔ قریب کھڑی ایک کشتی سے سندھی لوک گلوکارہ فوزیہ سومرو کی آواز بلند ہو رہی ہے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی سے تقریباً 130 کلومیٹع دور، داندو جیٹی کھوبھر کریک کے کنارے واقع ہے، جو ضلع ٹھٹہ میں دریائے سندھ کی باقی ماندہ دو کریکس میں سے ایک ہے۔
”اس کریک میں میٹھا پانی ہونا چاہیے، جو سمندر میں جا رہا ہو، لیکن اس میں میٹھے پانی کے بجائے سمندری پانی ہے۔۔“ زاہد ساکانی الجزیرہ کو بتاتے ہیں جب وہ اپنی آبائی بستی، حاجی قادر بخش ساکانی، جو کہ ٹھٹہ کی ذیلی تحصیل کھارو چھان میں واقع ہے، جانے کے لیے کشتی میں سوار ہوتے ہیں۔ یہ سفر تین گھنٹوں پر محیط ہے۔
چھ سال پہلے، 45 سالہ زاہد ایک کسان تھے، لیکن ان کی زمین، حاجی قادر بخش ساکانی گاؤں کے دیگر علاقوں سمیت، سمندر میں ڈوب گئی، جس کے باعث وہ نقل مکانی پر مجبور ہو گئے اور دندو جیٹی سے 15 کلومیٹر (9 میل) دور بگھان گاؤں جا بسے۔ وہاں، اپنی گزر بسر کے لیے انہیں درزی کا کام اختیار کرنا پڑا۔
اب کھارو چھان کی بندرگاہ ویران ہو چکی ہے۔۔ کوئی انسان نظر نہیں آتا، آوارہ کتے آزادانہ گھومتے ہیں، اور فعال کشتیوں سے متروک کشتیاں زیادہ ہیں۔ زاہد کبھی کبھار کھارو چھان آتے ہیں تاکہ اپنے والد اور دیگر آباؤ اجداد کی قبروں پر حاضری دے سکیں۔
ساکانی بندرگاہ پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں، ”ہم نے یہاں 200 ایکڑ (81 ہیکٹر) زمین پر کاشتکاری کی اور مویشی پالے، لیکن سب کچھ سمندر میں ڈوب گیا۔“
کبھی کھارو چھان ایک خوشحال علاقہ تھا، جہاں 42 دیہات (گاؤں) آباد تھے، مگر اب ان میں سے صرف تین باقی بچے ہیں۔ باقی تمام گاؤں سمندر برد ہو گئے، جس کے باعث ہزاروں افراد کو دوسرے گاؤں یا کراچی ہجرت کرنا پڑی۔
سرکاری مردم شماری کے مطابق، 1988 میں کھارو چھان کی آبادی 26,000 تھی، جو 2023 میں کم ہو کر 11,403 رہ گئی۔
صرف کھارو چھان ہی نہیں بلکہ گزشتہ دہائی میں سندھ ڈیلٹا کے درجنوں گاؤں سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔
نئے نہری منصوبے
اب، پہلے سے ہی کمزور اس ماحولیاتی نظام کو ایک نئے خطرے کا سامنا ہے۔
گرین پاکستان انیشی ایٹو کے تحت، پاکستانی حکومت اگلے تین سے پانچ سالوں میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور بحرین سے 6 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری حاصل کرنا چاہتی ہے تاکہ کارپوریٹ فارمنگ کے ذریعے 15 لاکھ ایکڑ (600,000 ہیکٹر) بنجر زمین کو قابل کاشت بنایا جا سکے اور ملک بھر میں موجود 50 ملین ایکڑ (20 ملین ہیکٹر) زرعی زمین کو جدید مشینی کاشتکاری سے آراستہ کیا جا سکے۔
اس منصوبے کے تحت مجموعی طور پر 48 لاکھ ایکڑ (1.9 ملین ہیکٹر) بنجر زمین کو سیراب کرنے کے لیے چھ نہریں تعمیر کی جائیں گی، سندھ، بلوچستان اور پنجاب میں دو دو نہریں۔ ان میں سے پانچ نہریں دریائے سندھ پر ہوں گی، جبکہ چھٹی نہر دریائے ستلج کے ساتھ تعمیر کی جائے گی تاکہ پنجاب کے سب سے زیادہ آبادی والے علاقے، چولستان کے صحرا کو سیراب کیا جا سکے۔
1960 کے سندھ طاس معاہدے کے مطابق، جو عالمی بینک کی ثالثی میں بھارت اور پاکستان کے درمیان طے پایا تھا، دریائے ستلج کا پانی بنیادی طور پر بھارت کی ملکیت ہے۔ یہ ان پانچ دریاؤں میں شامل ہے جو بھارت میں جنم لیتے ہیں اور پاکستان میں دریائے سندھ میں جا گرتے ہیں۔ اس معاہدے کے تحت، ستلج کے ساتھ ساتھ راوی اور بیاس کے پانیوں پر بھی بھارت کا حق ہے، جبکہ چناب، جہلم اور خود دریائے سندھ کا پانی پاکستان کے حصے میں آتا ہے۔
تاہم، ستلج مون سون کے دوران بھارت سے پاکستان میں پانی لے کر آتا ہے، اور چولستان تاریخی طور پر بارش کے پانی پر انحصار کرتا رہا ہے۔
اوبھایو خشک، جو کہ ایک سابقہ آبپاشی انجینئر ہیں، کہتے ہیں، ”وہ دریائے سندھ سے پانی چناب کے ذریعے ستلج کی طرف موڑیں گے، اور پھر اسے چولستان کینال میں منتقل کریں گے، آپ مون سون کے سیلابی پانی پر انحصار کرتے ہوئے نیا آبپاشی نظام نہیں بنا سکتے۔“
دوسری جانب، گرین پاکستان انیشی ایٹو کے تحت چولستان میں کارپوریٹ فارمنگ کا آغاز ہو چکا ہے، اور حکام نے چولستان کے صحرا میں 6 لاکھ ایکڑ (24,000 ہیکٹر) زمین کو سیراب کرنے کے لیے 4,121 کیوسک پانی کی منظوری دے دی ہے ، جو پاکستان کے دوسرے سب سے بڑے شہر لاہور سے بھی بڑا رقبہ ہے۔
سندھ کے نمائندے اور 1992 میں قائم کیے گئے انڈس ریور سسٹم اتھارٹی (IRSA) کے رکن، محمد احسان لغاری نے اس اقدام کی شدید مخالفت کی ہے۔
انہوں نے سوال اٹھایا، ”1999 سے 2024 تک، کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا جب پاکستان کو پانی کی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑا ہو، خاص طور پر سندھ اور بلوچستان میں گرمیوں کے دوران 50 فیصد تک پانی کی کمی رہی ہے۔ ایسے حالات میں، اس مجوزہ نہری نظام کے لیے پانی کہاں سے آئے گا؟“
سندھ حکومت نے مشترکہ مفادات کونسل (CCI) کو ایک خط میں اس منصوبے پر تنقید کی ہے۔ یہ آئینی ادارہ وفاقی حکومت اور صوبوں کے درمیان تنازعات حل کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ سندھ حکومت نے مؤقف اختیار کیا کہ انڈس ریور سسٹم اتھارٹی (IRSA) کو پانی کی دستیابی کے سرٹیفکیٹ جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں۔
سی سی آئی کی سربراہی وزیرِاعظم کرتے ہیں، جبکہ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور تین وفاقی وزراء اس کے رکن ہوتے ہیں۔
سندھ کے وزیرِ آبپاشی، جام خان شورو نے خبردار کیا کہ چولستان کینال ”سندھ کو بنجر بنا دے گی۔“ تاہم، وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی، احسن اقبال نے سندھ حکومت کے اعتراضات کو ”بے بنیاد“ قرار دیا اور کہا کہ نئی نہروں سے سندھ کے پانی کے حصے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔
مگر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے آزاد ماحولیاتی اور آبی امور کے ماہر حسن عباس کے مطابق، چولستان کینال ایک غیر سائنسی منصوبہ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ نہری نظام کی تعمیر کے لیے ہموار اور مستحکم زمین درکار ہوتی ہے، نہ کہ چولستان جیسے ریتیلے ٹیلے۔
”پانی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ کسی ریتیلے ٹیلے پر کیسے چڑھے،“ عباس نے کہا۔
ڈیلٹا کی تباہی
دریائے سندھ ہزاروں سال سے بہہ رہا ہے اور اس نے کبھی جدید پاکستان، افغانستان اور بھارت کے علاقوں میں پھیلی ہوئی قدیم انسانی تہذیب کو پروان چڑھایا تھا۔
جب برطانوی سامراج نے دو صدیوں قبل برصغیر کو نوآبادی بنایا، تو انہوں نے دریائے سندھ کا قدرتی بہاؤ بھی تبدیل کر دیا۔ انہوں نے بند تعمیر کیے اور اس کے راستے کو موڑنے کے منصوبے بنائے۔ 1947 میں آزادی کے بعد، انہی نوآبادیاتی پالیسیوں کو پاکستان میں بھی جاری رکھا گیا، اور مزید بیراج، ڈیم اور نہریں بنائی گئیں، جن کی وجہ سے دنیا کے پانچویں بڑے دریائی ڈیلٹا، سندھ ڈیلٹا، کی تباہی شروع ہو گئی۔
”ایک ڈیلٹا ریت، گاد اور پانی سے بنتا ہے۔ دریائے سندھ کے ڈیلٹا کی تباہی کا عمل 1850 میں اس وقت شروع ہوا جب برطانوی راج نے نہری نظام قائم کیا۔ اس کے بعد پاکستان، بھارت یا چین میں جو بھی نہر بنی، اس نے سندھ ڈیلٹا کی بربادی میں حصہ ڈالا،“ حسن عباس نے الجزیرہ کو بتایا۔
دریائے سندھ کا ماخذ چین کے زیرِ انتظام تبت کے علاقے میں ہے، جہاں چین نے بھی اس پر ایک ڈیم تعمیر کیا ہے۔
امریکا-پاکستان سینٹر فار ایڈوانسڈ اسٹڈیز ان واٹر (USPCAS-W) کی 2019 کی ایک تحقیق کے مطابق، 1833 میں سندھ ڈیلٹا کا رقبہ 13,900 مربع کلومیٹر (5,367 مربع میل) تھا، جو 2018 میں سکڑ کر محض 1,067 مربع کلومیٹر (412 مربع میل) رہ گیا، یعنی اپنے اصل رقبے کا 92 فیصد حصہ ختم ہو چکا ہے۔
”ڈیلٹا کھلے ہاتھ کی طرح ہوتا ہے، اور اس کی کھاڑیاں (creeks) اس کی انگلیاں ہیں جو سمندر میں گرتی ہیں،“ زاہد ساکانی نے کہا۔ ”ان انگلیوں کے درمیان کا خلا لاکھوں انسانوں، جانوروں اور دیگر مخلوقات کا مسکن ہے، لیکن یہ تیزی سے سکڑ رہا ہے۔“
زمین کے بگڑتے ہوئے حالات کے باعث، مقامی لوگ مجبور ہو کر دریا کے اوپری حصے کی طرف ہجرت کرنے لگے۔ لیکن سب کے لیے نقل مکانی ممکن نہ تھی۔ جو لوگ ڈیلٹا میں رہ گئے، انہوں نے زراعت چھوڑ کر دوسرے پیشے اختیار کر لیے، جن میں سب سے زیادہ مچھلی پکڑنے کا کام کیا جانے لگا۔
صدیق کاتیار ، جو 55 سال کے ہیں اور دندو جیٹی کے قریب حاجی یوسف کاتیار گاؤں کے رہائشی ہیں، تقریباً 15 سال پہلے ماہی گیر بنے۔
”مجھے یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں کبھی چند ہی کشتیاں ہوتی تھیں۔ اب ہر گھر میں کشتیاں ہیں اور ماہی گیروں کی تعداد دن بدن بڑھ رہی ہے،“ انہوں نے الجزیرہ کو بتایا۔
روزگار کا خاتمہ
عربین سی کے ساتھ سنہڑی کھاڑی میں، جو دندو جیٹی سے سات گھنٹے کی کشتی کی مسافت پر واقع ہے، درجن بھر عارضی جھونپڑیوں میں وہ لوگ رہتے ہیں جنہیں ’ماہی گیری مزدور‘ کہا جاتا ہے۔
ناتھی ملاح، جو 50 سال کی ہیں اور ٹھٹہ کے کیٹی بندر علاقے کے جوھو گاؤں کی رہائشی ہیں، انہی ماہی گیر مزدوروں میں شامل ہیں۔ وہ ایک چھوٹی لوہے کی سلاخ کو نمک کے مرتبان میں ڈبوتی ہیں، پھر اسے ریتلی زمین میں داخل کرتی ہیں۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد، وہ سلاخ کو واپس کھینچتی ہیں اور تیزی سے ایک چھوٹی آبی مخلوق پکڑ لیتی ہیں، جسے مقامی زبان میں "ماروآڑی” کہا جاتا ہے (انگریزی میں Razor Shell)۔ یہ لمبی، پتلی اور مستطیل شکل کی ہوتی ہے، جو پرانے زمانے کے استرے جیسی دکھائی دیتی ہے۔
ناتھی اپنے شوہر اور چھ بچوں کے ساتھ مل کر ”ماروآڑی“ پکڑتی ہیں، جو ماہی گیروں کے مطابق صرف چین کو برآمد کی جاتی ہے۔ ناتھی کے کسی بھی بچے کا اسکول جانا ممکن نہیں، کیونکہ ان کا پورا خاندان روزانہ 10 سے 12 گھنٹے ایک مقامی ٹھیکیدار کے لیے کام کرتا ہے، جو انہیں کچھ مقدار میں نمک اور پینے کا پانی فراہم کرتا ہے۔
مارواری کا نرخ 42 پاکستانی روپے (تقریباً 15 امریکی سینٹ) فی کلو ہے، اور ملاح خاندان کا ہر فرد روزانہ 8 سے 10 کلو جمع کر لیتا ہے، جس سے انہیں بمشکل گزر بسر کے لیے رقم ملتی ہے۔ ناثی نے تقریباً پانچ سال پہلے یہ کام شروع کیا، جب جوھو میں ان کا ماہی گیری کا پیشہ نقصان میں چلا گیا۔
محمد صدیق ملاح، جو ناتھی ملاح کے شوہر ہیں، کا کہنا ہے کہ زمین کی بگڑتی ہوئی حالت نے لوگوں کو زراعت چھوڑ کر ماہی گیری اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ ”میرے جوانی کے دنوں میں جتنے ماہی گیر سمندر میں ہوتے تھے، آج ان کی تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے،“ 55 سالہ صدیق نے الجزیرہ کو بتایا۔
ورلڈ بینک کی 2019 کی رپورٹ کے مطابق، انڈس ڈیلٹا کی تباہی کے باعث ماہی گیری کی پیداوار 1951 میں 5,000 ٹن سالانہ سے گھٹ کر اب محض 300 ٹن رہ گئی ہے، جس کے نتیجے میں پاکستان کو سالانہ دو ارب ڈالر کا نقصان ہو رہا ہے۔
ناتھی کہتی ہیں، ”ایک وقت تھا جب ہمارے مرد سمندر میں جاتے اور دس دن بعد واپس آ جاتے، اب وہ مہینوں تک واپس نہیں آتے۔“
فصلوں کے لیے پانی نہیں
اللہ بخش کلمتی، جو 60 سال کے ہیں اور دندو جیٹی میں رہتے ہیں، ٹماٹر، مرچ، کچھ سبزیاں اور پان کے پتے اگاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میٹھا پانی صرف مون سون کے دو مہینوں میں دستیاب ہوتا ہے۔
لیکن کلمتی کے پان کے باغ کو ہر دو ہفتے بعد پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انہوں نے شکایت کی، ”اب ایک مہینہ ہو چکا ہے اور پودوں کے لیے پانی نہیں ہے۔“
1991 کے Water Apportionment Accord (WAA)، جو پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، کے مطابق، ہر سال کم از کم 10 ملین ایکڑ فٹ (MAF) پانی کوٹری بیراج سے آگے چھوڑنا ضروری ہے تاکہ نیچے کے ڈیلٹا کے ماحولیاتی نظام کو برقرار رکھا جا سکے۔
1991 میں سوئٹزرلینڈ میں قائم International Union for Conservation of Nature (IUCN) نے سالانہ 27 ملین ایکڑ فٹ (MAF) پانی چھوڑنے کی سفارش کی تھی، لیکن یہ ہدف کبھی حاصل نہ ہو سکا۔ مزید برآں، Indus River System Authority (IRSA) کے اعداد و شمار کے مطابق، گزشتہ 25 سالوں میں سے 12 سال ایسے تھے جن میں پانی کا بہاؤ 10 MAF سے بھی کم تھا کیونکہ حکام نے اسے سمندر تک پہنچنے سے پہلے ہی دیگر مقاصد کے لیے موڑ دیا۔
محقق حسن عباس، جو پانی کی قلت کو ڈیموں اور بیراجوں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، کا کہنا ہے ”دس MAF پانی انڈس ڈیلٹا کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہری نظام سے پہلے، ڈیلٹا کو سالانہ 180 سے 200 MAF پانی ملتا تھا، اور اسے بقا کے لیے اتنی ہی مقدار میں پانی کی ضرورت ہے۔“
انہوں نے مزید کہا، ”ہمارے پاس پچھلی صدی کے مقابلے میں 10 فیصد زیادہ پانی موجود ہے۔ لیکن نہر پر نہر بنانے سے پانی کا بہاؤ منتشر ہو گیا، جس کے نتیجے میں بالائی علاقوں میں زمین دلدلی ہو گئی اور ڈیموں میں گاد بھر گئی۔“
پاکستان کا فرسودہ آبپاشی نظام اور پانی کا زیاں
سندھ میں ایک کاشتکار انجمن کے صدر، محمود نواز شاہ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا آبپاشی نظام ”پرانا اور فرسودہ“ ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا، ”ہمارے ہاں اوسطاً فی مکعب میٹر 130 گرام اناج پیدا ہوتا ہے، جبکہ پڑوسی بھارت میں یہی مقدار 390 گرام ہے۔“
شاہ نے وضاحت کی کہ پاکستان کو آبپاشی کا نظام وسعت دینے کے بجائے موجودہ پانی کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے اور وسائل کا مؤثر انتظام کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے International Water Management Institute کے ایک مطالعے کا حوالہ دیتے ہوئے کہا، ”پاکستان اپنے کل پانی کا 90 فیصد زراعت میں استعمال کرتا ہے، جبکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ 75 فیصد استعمال کیا جاتا ہے۔“
انہوں نے مزید کہا، ”کئی علاقوں میں نہریں تو موجود ہیں، مگر پانی وقت پر نہیں پہنچتا۔ مثال کے طور پر، انڈس ڈیلٹا میں پہلے سے موجود زرخیز زمینوں کے لیے ہی پانی دستیاب نہیں ہے۔ پاکستان کو پانی کے تحفظ اور زرعی پیداوار بڑھانے کے طریقے سیکھنے ہوں گے۔“
داندو جیٹی کی واپسی پر
داندو جیٹی پر، زاہد سکانی ابھی ابھی اپنے آبائی گاؤں کھارو چھان کا دورہ مکمل کر کے واپس پہنچے تھے۔ گھر جانے سے پہلے، وہ داندو سے کچھ تازہ مچھلی خریدنا چاہتے تھے، مگر اس دن سمندر سے کوئی کشتی نہیں آئی تھی۔
انہوں نے بتایا ”ایک وقت تھا جب ہم پلّا مچھلی فقیروں میں تقسیم کرتے تھے، مگر اب ہمیں یہاں مچھلی بھی دستیاب نہیں۔“
ادھر، جوار کی اونچی لہریں کھوبھر کریک کو سمندر کی مانند بنا دیتی ہیں، جو اب بگھان سے صرف 7-8 کلومیٹر (4-5 میل) کے فاصلے پر رہ گیا ہے،بگھان، جہاں زاہد نے اپنا نیا ٹھکانہ بنایا ہے۔
انہوں نے بتایا ”جب ہم کھارو چھان سے یہاں منتقل ہوئے تھے تو سمندر چودہ پندرہ کلومیٹر دور تھا، اگر نیچے میٹھا پانی ختم ہو گیا تو سمندر زمین کو مزید کھا جائے گا، اور اگلے 15 سال میں بگھان بھی ختم ہو جائے گا۔ ہمیں پھر کسی اور جگہ جانا پڑے گا۔“
”دریائے سندھ پر مزید نہریں اور رکاوٹیں بنانے سے پانی کا بہاؤ مکمل طور پر رک جائے گا۔۔ یہ انڈس ڈیلٹا کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا۔“
ماخذ: الجزیرہ (منیش کمار کی رپورٹ) ترجمہ: امر گل