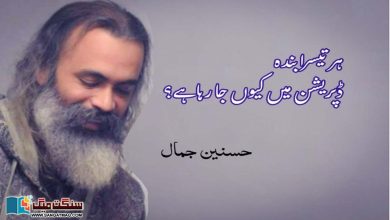ماں بولی کے اس پڑاؤ میں ہم بات کریں گے برصغیر میں زبان، اقتدار اور تاریخ کی، اور اس حصے میں قدیم ہندوستان سے تقسیم تک کا ذکر کریں گے۔
زبان کبھی محض الفاظ کا مجموعہ نہیں رہی۔ انسانی تاریخ میں زبان ہمیشہ طاقت، علم اور اختیار کے ساتھ جڑی رہی ہے۔ جس کے پاس اقتدار تھا، اس کی زبان کو برتری ملی، اور جس کی زبان کمزور پڑی، اس کی تاریخ، یادداشت اور شناخت بھی کمزور کر دی گئی۔ برصغیر کی تاریخ کو اگر اس زاویے سے دیکھا جائے تو یہ صرف سلطنتوں اور جنگوں کی تاریخ نہیں، بلکہ زبانوں کے عروج، زوال اور مزاحمت کی کہانی بھی ہے۔
قدیم ہندوستان میں زبان کا معاملہ شروع ہی سے طاقت کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ ویدک عہد میں سنسکرت کو مذہب، علم اور فلسفے کی زبان قرار دیا گیا، مگر یہ زبان عوام کی نہیں تھی۔ سنسکرت کو جان بوجھ کر ایک خاص طبقے تک محدود رکھا گیا تاکہ علم، مذہب اور سماجی اختیار عوام کی پہنچ سے باہر رہے۔ عام انسان کی بولیاں جیسے پراکرت، اپ بھرنش اور دیگر مقامی زبانیں زندگی میں تو زندہ رہیں، مگر انہیں علم اور تاریخ کے مراکز میں جگہ نہ دی گئی۔
یہاں زبان محض اظہار کا ذریعہ نہیں رہی بلکہ طبقاتی دیوار بن گئی۔ جو سنسکرت جانتا تھا، وہ علم والا تھا، جو نہیں جانتا تھا، وہ سماجی طور پر کمتر سمجھا گیا۔ یوں زبان نے سماج میں برابری پیدا کرنے کے بجائے نابرابری کو مضبوط کیا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں زبان اور قوم کا فطری رشتہ ٹوٹنے لگتا ہے، کیونکہ جب زبان عوام سے چھن جائے تو وہ قوم کی نمائندہ نہیں رہتی۔
راجاؤں اور مہاراجاؤں کے عہد میں بھی یہی روایت قائم رہی۔ دربار کی زبان الگ تھی، عوام کی زبان الگ۔ تاریخ دربار کی زبان میں لکھی گئی، مگر عوام کی زندگی، ان کے دکھ، خوشی، محبت اور مزاحمت عوامی زبانوں میں محفوظ رہیں، مگر غیر تحریری صورت میں۔ اس غیر تحریری تاریخ کو ریاست نے کبھی سنجیدگی سے قبول نہیں کیا۔
یہی انجام خود سنسکرت کا ہوا۔ صدیوں تک مذہب اور اشرافیہ کی زبان رہنے کے بعد سنسکرت ایک زندہ بولی جانے والی زبان نہ رہ سکی۔ وہ کتابوں، منتر، رسومات اور مقدس متون تک محدود ہو گئی۔ یوں سنسکرت مری نہیں، مگر انسانوں کی زبان کے طور پر ختم ہو گئی۔ یہ ایک نہایت اہم حقیقت ہے کہ
”زبان صرف اس وقت زندہ رہتی ہے جب وہ عوام کی روزمرہ زندگی کا حصہ ہو، نہ کہ صرف مذہب یا ریاست کی ملکیت“۔
یہی مثال ہمیں برصغیر سے باہر بھی ملتی ہے۔ لاطینی (Latin) رومن سلطنت کی ریاستی، عدالتی اور علمی زبان تھی۔ یورپ کے بڑے حصے میں صدیوں تک لاطینی کو اقتدار حاصل رہا، مگر جب یہ زبان عوام کی بولی نہ رہی اور صرف کلیسا، فلسفہ اور اشرافیہ تک محدود ہو گئی تو آہستہ آہستہ ایک زندہ زبان کے طور پر ختم ہو گئی۔ آج لاطینی زندہ ہے، مگر بولی نہیں جاتی۔ اس کے بطن سے فرانسیسی، اطالوی اور ہسپانوی جیسی زبانیں پیدا ہوئیں، مگر خود لاطینی ایک مقدس یادگار بن کر رہ گئی۔
یہ دونوں مثالیں ہمیں ایک بنیادی اصول سکھاتی ہیں کہ
ریاستی سرپرستی، مذہبی تقدس یا علمی برتری بھی کسی زبان کو زندہ نہیں رکھ سکتی، اگر وہ عوام سے کٹ جائے۔
برصغیر میں مغل دور آیا تو فارسی ریاستی زبان بنی۔ عدالت، انتظامیہ اور علم فارسی میں منتقل ہوا۔ مقامی زبانیں جیسے تمل، پنجابی، سندھی، بنگالی، پشتو اور دیگر زبانیں عوامی سطح پر زندہ رہیں، مگر اقتدار کے ایوانوں سے باہر رہیں۔ اسی ماحول میں اردو نے جنم لیا، جو لشکر، بازار اور شہری میل جول کی زبان تھی۔ مگر رفتہ رفتہ ریاستی سرپرستی نے اردو کو بھی طاقت کے مرکز کے قریب کر دیا، اور دیگر مقامی زبانیں حاشیے پر چلی گئیں۔
مگر آج کی حقیقت یہ ہے کہ مقامی زبانیں آج بھی موجود ہیں، فارسی کہیں نہیں۔ مغل دور کے بعد فارسی زبان کی وہ حیثیت باقی نہ رہی جو کبھی اسے حاصل تھی۔
انگریز سامراج نے اس پورے نظام کو ایک نئے انداز میں استعمال کیا۔ انگریزی کو علم کے نام پر نہیں بلکہ اقتدار کے ہتھیار کے طور پر نافذ کیا گیا۔ جو انگریزی جانتا تھا، وہ حکمرانی کے قریب تھا، جو اپنی مادری زبان میں جیتا تھا، وہ پسماندہ ٹھہرا۔ مقامی زبانوں کو غیر ترقی یافتہ اور غیر مفید قرار دیا گیا۔ یہ نوآبادیاتی سوچ بعد میں نئی ریاستوں کو ورثے میں ملی۔
تحریکِ آزادی کے دوران زبان کا کردار نہایت پیچیدہ رہا۔ بھگت سنگھ جیسے کردار زبان کو طبقاتی شعور اور عوامی سیاست سے جوڑتے ہیں۔ گاندھی عوامی رابطے کے لیے ہندوستانی اور ہندی کی بات کرتے ہیں، مگر مسلم لیگ کی سیاست میں اردو کو مذہب کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اردو مسلمانوں کی واحد شناخت کے طور پر پیش کی گئی، حالانکہ مسلمان سندھی بھی تھے، پنجابی بھی، بنگالی بھی، اور ہندوستان کے طول و عرض میں دیگر زبانیں بولنے والے مسلمان بھی موجود تھے۔ مگر جاگیردار، ملا اور اشرافیہ نے زبان اور مذہب کو ملا کر سیاست کی، قوم اور زبان کو نہیں۔
یہیں سے وہ تضاد پیدا ہوا جو بعد میں ریاستی بحران کی شکل اختیار کر گیا۔ زبان کو قوم کی بنیاد بنانے کے بجائے، زبان کو اقتدار کا نشان بنا دیا گیا۔ تقسیم سے پہلے ہی یہ بیج بو دیا گیا تھا کہ ریاست زبانوں کے تنوع کو قبول نہیں کرے گی، بلکہ ایک زبان کو مرکز بنا کر باقی زبانوں کو حاشیے پر دھکیل دے گی۔
برصغیر کی تقسیم یوں محض جغرافیائی تقسیم نہیں تھی، بلکہ ایک فکری تقسیم بھی تھی، جس میں زبان، شناخت اور طاقت کے سوالات حل نہیں ہوئے بلکہ مزید الجھ گئے۔ نیپال اگرچہ براہِ راست تقسیم کا حصہ نہیں تھا، مگر برطانوی سامراج کے دائرۂ اثر میں رہا، اسی لیے سامراج کے جانے کے بعد وہ ایک الگ ریاست کے طور پر دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ ہندوستان اور پاکستان دو الگ ریاستیں بنیں، بنگال دو حصوں میں بٹا، پنجاب تقسیم ہوا، سندھ بھی تقسیم کے اثرات سے محفوظ نہ رہ سکا، کشمیر کا بدنصیب خطہ آج بھی طاقت کے ان دو ستونوں کے درمیان تختہ مشق بنا ہوا ہے اور گلگت بلتستان کے لوگ آج بھی اپنی بقا اپنی حیثیت اور اپنے زمین ِاور اس کے حق کے لیئے صدائیں دے رہے ہیں۔
بلوچستان کا کیس ذرا مختلف ہے۔ برطانیہ سامراج نے بلوچستان کو پہلے ہی دو حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ خان آف قلات کا بلوچستان، جہاں برطانیہ خان آف قلات کے ذریعے حکومت کرتا تھا، اس کا ایک حصہ افغانستان اور ایک حصہ ایران کو دے دیا گیا۔ برصغیر کی آزادی کے بعد بلوچستان چند مہینے آزاد رہنے کے باوجود جبری طور پر پاکستان میں شامل کیا گیا۔ یوں بلوچ عوام تین حصوں میں تقسیم ہو گئے: افغانستان، ایران اور پاکستان۔ اس تقسیم کے ساتھ بلوچ قوم، بلوچی اور براہوی زبانیں بھی تقسیم ہو گئیں۔ یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ ریاستیں زبان اور قوم کے رشتے کو رضامندی سے نہیں، طاقت سے بدلنا چاہتی تھیں۔
یہی وہ پس منظر ہے جس کے بغیر ہم نہ پاکستان کی زبان پالیسی کو سمجھ سکتے ہیں، نہ ہندوستان کی۔ تقسیم کے بعد بھی زبانوں کے ساتھ وہی نوآبادیاتی، مرکزی اور اشرافیائی رویہ برقرار رہا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ اب حاکم بدل چکے تھے، نظام نہیں۔
(جاری ہے)