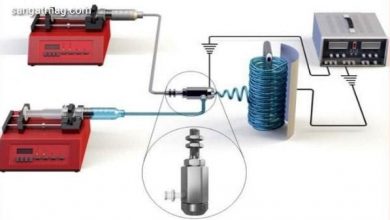عرشے پر بجھے بجھے بلب کی روشنی میں چار شخص بیٹھے تھے۔ ایک بھورے بالوں والی خاتون، ایک قصاب جس سے کچے گوشت کی بساند آ رہی تھی، ایک گنجے سر والا پروفیسر منہ میں پائپ تھامے، ایک گورا چٹا نوجوان۔۔ چاروں کے پہنچنے سے پہلے ہی آخری اسٹیمر چھوٹ چکا تھا۔ اس کشتی کے کپتان نے، جو نیند میں دھت تھا، فی کس پانچ لیروں کا مطالبہ کیا تو چاروں کود کر جھٹ کشتی میں سوار ہو گئے۔
انجن سے چلنے والی یہ کشتی اندھیرے میں پانی کو چیرتے آگے بڑھ رہی تھی۔ بھورے بالوں والی عورت ٹانگ پر ٹانگ ٹکائے سگریٹ کے کش لگا رہی تھی۔ سگریٹ کے دھوئیں کو ایک شاندار انداز میں رات کی خنکی کی طرف چھوڑ رہی تھی۔
گورے چٹے نوجوان کی نگاہیں خاتون کے گھٹنوں پر مرکوز تھیں، گو اس کا ذہن ابھی تک شراب خانے کی اس ویٹرس کی بھری بھری رانوں میں الجھا ہوا تھا، جس سے وہ تھوڑی ہی دیر پہلے جدا ہوا تھا۔ پروفیسر کا دماغ اس مقالے میں پھنسا ہوا تھا، جو وہ ٹرام میں سفر کے دوران پڑھ چکا تھا۔ قصاب ادھر مونگ پھلی کھار ہا تھا اور ادھر اس بل کے بارے میں سوچ رہا تھا جو بکروں کے تَھوک کے بیوپاری نے اسے بھیجا تھا۔ ’چلو قرامانی بکرے کی ڈیڑھ سو لیرے مان بھی لو۔۔ مگر اس ناہنجار نے پہاڑی بکروں کی قیمت ایک سوا سی کے حساب سے کیسے لگائی ہے؟‘
رات کے وقت آسمان پر ستاروں کا نام و نشان نہیں تھا۔ سمندر کی موجوں میں معمولی سا اضطراب دکھائی دیتا تھا۔ کشتی سے ٹکراتی چھوٹی چھوٹی لہروں کی پھوار کبھی کبھی ترپال کے گدوں کو بھگو جاتی تھی۔ کشتی استنبول کے ساحلی قصبوں کو پیچھے چھوڑتی جزیروں کی جانب بڑھ رہی تھی۔ بھورے بالوں والی خاتون کو سردی لگی ہوگی کہ وہ یکدم عرشے سی اٹھی اور ہوا سے اڑتی اسکرٹ کو تھامے تھامے کمرے کی طرف لپکی۔ اندر داخل ہوتے ہی اس کا سر چکرانے لگا۔ کیونکہ کمرہ جلتے پٹرول اور دہکتے لوہے کی ملی جلی بو سے بھرا ہوا تھا۔ خاتون نے فوراً ایک کھڑکی کھولی اور اس کے بالمقابل بیٹھ گئی۔
چاملی جا کی ڈھلانوں سے ہوائی جہاز مار گرانے والی توپوں کی دو عدد سرچ لائٹیں اندھیرے گھپ آسمان کو کھنگال رہی تھیں۔ ان میں سے ایک آہستہ آہستہ دائیں سے بائیں حرکت کر رہی تھی، جبکہ دوسری بائیں سے دائیں سرک رہی تھی۔ دونوں شعاعیں وسط میں ایک جگہ پہنچ کر اکھٹی ہوتیں تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیا جاتیں۔
خاتون اسی نظارے سے لطف اندوز ہونے میں مگن تھی کہ قریب ہی سے جگنو کی طرح کی کوئی عجیب سی روشنی اڑ کر سمندر میں جا گری۔ اس کے بعد ایک اور پھر اور یکے بعد دیگرے روشنی کی چنگاریوں کا ایک لا متناہی سلسلہ جاری ہو گیا۔ عورت اپنے خیالوں میں ڈوبی کچھ دیر ایک دوسرے کا پیچھا کرنے والے ان روشنی کے مکوڑوں کو ایک ایک کر کے کالے سیاہ سمندر میں گرتے اور پھر چینی سیاہی کی طرح پگھلتے دیکھتی رہی۔ پھر اچانک اسے پگھلتے لوہے کی وہ بو یاد آئی، جس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ اچھل کر اپنی جگہ سے اٹھی اور کپتان کے کمرے کی طرف لپکی۔ اس کمرے کے دروازے میں سے ہلکا سے دھواں باہر آر ہا تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے کے ساتھ چمٹ گئی۔ تب اس نے چہرہ جھلساتے دھوئیں میں سے دیکھا کہ اندر کپتان اور اس کا میٹ، جو رسے سے کشتی کو ساحل سے باندھنے کا کام کرتا ہے، دونوں خون پسینے سے تر زمین پر آلتی پالتی مارے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے لئے اسے یوں محسوس ہوا، جیسے وہ بے ہوش ہونے کو ہے، پھر ’آگ آگ۔۔ بچاؤ بچاؤ۔۔‘ چِلّاتی کمرے سے باہر کود گئی۔
عورت کے چِلّانے کی وجہ سے عرشے پر بھگدڑ مچ گئی۔ وہ چونکہ کپتان کے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ آئی تھی، اس لیے اب دھواں اتنا گاڑھا ہو گیا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا۔ قصاب نے گھبراہٹ میں اپنی سیٹ کی گدی اٹھا کر سینے سے بھینچ رکھی تھی۔ پروفیسر صاحب کشتی کا واحد حفاظتی جیکٹ اٹھا کر زیبِ تن کر چکے تھے۔ نوجوان کے منہ سے بوکھلاہٹ کے باعث پائپ نیچے گر چکا تھا۔ بھورے بالوں والی خاتون نوجوان کی طرف بھاگی اور منت سماجت کرتے ہوئی بولی، ’’مجھے بچا لو۔۔۔ مجھے بچا لو۔۔۔۔۔ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔‘‘
نو جوان تھر تھر کانپتی آواز میں بولا، ’’میں بھی نہیں جانتا تیرنا۔‘‘ حالانکہ وہ تھوڑا بہت تیرنا جانتا تھا۔ کم از کم اتنا تو ضرور جانتا تھا کہ آدھ گھنٹے کے قریب پانی کی سطح پر رہ سکتا، مگر تنِ تنہا۔
اس سے مایوس ہو کر خاتون نے قصاب سے مدد کی امید باندھی، مگر وہ اس وقت دونوں ہاتھ پھیلا کر منت مان رہا تھا۔ ”اگر اس مصیبت سے میں زندہ بچ جاؤں تو اپنی جان کا صدقہ تین بھیڑیں قربان کروں گا۔‘‘
سب سے بری حالت پروفیسر کی تھی حالانکہ اسے اپنے بڑا بہادر ہونے کا دعویٰ تھا۔ ابھی اسی روز صبح یہ پڑھاتے ہوئے کہ سقراط نے کیسے زندگی کو حقیر جان کر ٹھکرا دیا تھا، اس بات کا دعویٰ کیا تھا کہ ایک حقیقی فلسفی کے لئے ایسی راہِ عمل اختیار کرنا بالکل معمولی بات ہوتی ہے اور یہ کہ وہ خود بھی سقراط کی طرح ہنستے مسکراتے موت کا خیر مقدم کر سکتا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ طلباء کے ساتھ ساتھ وہ خود اپنے آپ کو بھی اپنے اس طرزِ عمل کے بارے میں یقین دلانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔
اس وقت میٹ بالٹی میں پانی بھر رہا تھا۔ عورت اس کے بالوں سے اٹے سینے سے چمٹ کر چِلّائی۔ ’’خدا کا واسطہ ہے مجھے اکیلے چھوڑ کر نہ چلے جانا۔ ہر گز نہ جانا مجھے چھوڑ کر۔‘‘
وہ یونہی شور مچا رہی تھی کہ ادھر سے کپتان کی آواز سنائی دی، ’’ہنگامہ مت کرو۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم لوگ ضرور اس کشتی کو ڈبو کے رہو گے۔‘‘
غصے میں ہونے کے باوجود کپتان کی آواز میں کوئی ایسا جادو تھا، جس سے سب کو سلامتی کا پیغام مل رہا تھا۔ کیا آگ پر قابو پا لیا گیا تھا؟ جی ہاں، آگ بجھا لی گئی ہوگی ورنہ کپتان کو انہیں یوں جھڑکیں پلانے کی مہلت کیسے مل سکتی تھی۔۔ اور پھر میٹ بالٹی میں بچا ہوا پانی دوبارہ سمندر میں کیسے انڈیل سکتا تھا؟
کپتان پھر بولا، ’’خدا جانے کیسے لوگوں سے پالا پڑا ہے۔‘‘
پروفیسر کے مطابق کپتان کا غصہ بالکل جائز تھا۔ وہ اپنا کالر سیدھا کرتے ہوئے کھؤ کھؤ کر کے کھانسا اور ابھی کہنے ہی کو تھا کہ ’حضرات، یہ گھبراہٹ چہ معنی دارد؟ خاموش ہو جائیے۔‘ مگر اچھا ہی ہوا کہ وہ یہ الفاظ نہ کہہ پایا۔ کہتا بھی کیسے؟ ابھی تک حفاظتی جیکٹ اس کے جسم پر ہی رونق افروز تھا۔
کشتی کا انجن ایک دو بار رکا اور پھر دوبارہ مزے مزے سے چلنے لگا۔ کپتان اب واپس اپنی جگہ پر پہنچ چکا تھا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے تک آگ کی وجہ سے لال سرخ ہو جانے والی کشتی کے انجن کو، اور شور و غوغا کرنے والے مسافروں کو جلی کٹی سنا رہا تھا، مگر کسی نے ذرا بھی برا نہ منایا۔ برا بھلا کہتا ہے تو کہتا رہے، گالیاں دیتا ہے تو دیتا رہے گا۔ چاہے تو بیشک سب کو پیٹ بھی لے۔ کیا یہی کچھ کم ہے کہ اس نے ہم سب کی جان بچا لی ہے۔
میٹ اب اپنی قمیص کے بازو سے پسینہ خشک کر رہا تھا۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ اس پورے ہنگامے میں کپتان سے کہیں زیادہ یہ بیچارا تھکن کا شکار ہوا تھا۔ کوئی پندرہ منٹ بعد ہر چیز اپنے معمول پر آ چکی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ہوا گلا گھونٹتے کثیف دھوئیں کے ساتھ ساتھ موت کے خطرے کو بھی عرشے پر سے اچک کر اڑا لے گئی ہے۔
عرشے پر بجھے بجھے بلب کی روشنی میں اب پھر وہی چار مسافر بیٹھے تھے۔ چار مسافر، جو سب کے سب اپنے آپ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ خاتون بظاہر خاصے سکونِ قلب سے ہمکنار ہو چکی تھی۔ وہ سگریٹ بھی پی رہی ہوتی، اگر اس کے ہاتھ کچھ ضرورت سے زیادہ ہی کانپنا نہ شروع کر دیتے۔ نوجوان حسبِ سابق پائپ کے کش لگا رہا تھا البتہ اب اس کی نگاہیں خاتون کے گھٹنوں پر مرکوز نہیں تھیں۔ پروفیسر پیچھے گھر میں اپنی منتظر گول مٹول بیوی اور لال لال گالوں والے بچوں کے بارے میں سوچ رہا تھا، جنہیں اب وہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ پیار کرنے لگا تھا۔
جہاں تک قصاب کا تعلق ہے، تو وہ تھوڑی دیر پہلے مانی گئی منت کی تین بھیڑوں کی تعداد گھٹا کر دو کرنے کی خاطر اپنے ضمیر کو بہکانے میں مصروف تھا۔ وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب بھی ہو چکا تھا۔۔ اور کامیاب بھی اس حد تک کہ جونہی بڑے جزیرے کی روشنیاں دکھائی دینے لگیں، قصاب کی قربانی کی بھیڑوں کی تعداد گھٹ کر ایک ہو گئی۔ اس ایک بھیڑ کو بھی وہ عیدِ قربان پر ذبح کرنے کا عہد کر چکا تھا۔
منزلِ مقصود پر پہنچتے ہی کشتی پر سے کود کر نیچے اترنے والا پہلا شخص پروفیسر تھا۔ اس کے بعد گورا چٹا نوجوان جو سیٹیاں بجاتا، ڈانس میوزک کی دھنیں سناتا چلا جا رہا تھا۔ قصاب بھاگتا بھاگتا، اچھلتا کودتا، ایک بچے کی طر ح دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ بھورے بالوں والی خاتون کی باری سب سے آخر میں آئی۔ اسے ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ ڈولتی کشتی میں سے چھلانگ لگا کر ساحل پر جا اترے۔ میٹ نے ہاتھ بڑھا کر اس کی مدد کرنے کی پیشکش کی مگر خاتون بھلا اس پسینے کی بُو والے، میلے کچیلے کپڑوں میں ملبوس شخص کا بازو تھامنے پر کیسے راضی ہو سکتی تھی؟ اس نے ہچکچاتے ہوئے اناڑیوں جیسی جست لگائی اور خود کو ساحل پر پہنچا دیا۔ پھر اپنی جوتی کی ایڑیوں کے بل نہایت پُر وقار طریقے سے خراماں خراماں ساحل سے دور ہوتی چلی گئی۔