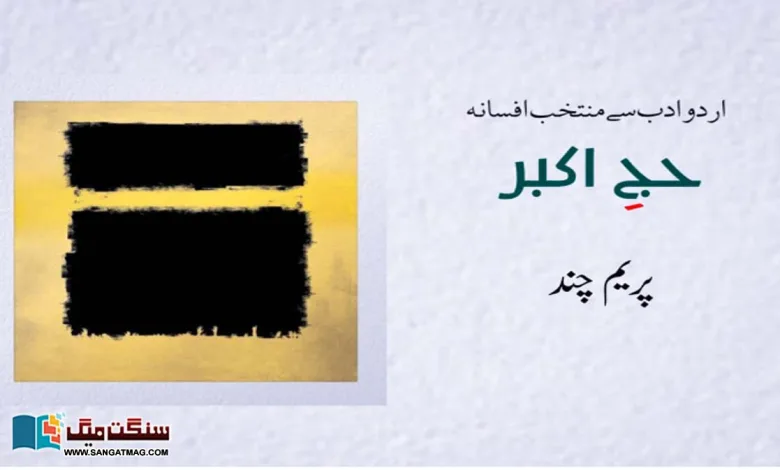
منشی صابر حسین کی آمدنی کم تھی اور خرچ زیادہ۔ اپنے بچہ کےلیے دایہ رکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے، لیکن ایک تو بچہ کی صحت کی فکر اور دوسرے اپنے برابر والوں سے ہیٹے بن کر رہنے کی ذلت اس خرچ کو برداشت کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بچہ دایہ کو بہت چاہتا تھا۔ ہر دم اس کے گلے کا بار بنا رہتا۔ اس وجہ سے دایہ اور بھی ضروری معلوم ہوتی تھی۔ مگر شاید سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ وہ مروت کے باعث دایہ کو جواب دینے کی جرات نہ کرسکتے تھے۔
بڑھیا ان کے یہاں تین سال سے نوکر تھی۔ اس نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش کی تھی۔ اپنا کام دل و جان سے کرتی تھی۔ اسے نکالنے کا کوئی حیلہ نہ تھا اور خواہ مخواہ کھچڑ نکالنا صابر جیسے حلیم شخص کے لیے غیر ممکن تھا۔ مگر شاکرہ اس معاملہ میں اپنے شوہر سے متفق نہ تھی۔ اسے شک تھا کہ دایا ہم کو لوٹے لیتی ہے۔ جب دایا بازار سے لوٹتی تو وہ دہلیز میں چھپی رہتی کہ دیکھوں اٹا چھپا کر تو نہیں رکھ دیتی۔ لکڑی تو نہیں چھپا دیتی۔ اس کی لائی ہوئی چیز کو گھنٹوں دیکھتی، پچھتاتی ، بار بار پوچھتی اتنا ہی کیوں؟ کیا بھاؤ ہے؟ کیا اتنا مہنگا ہو گیا؟ دایہ کبھی تو ان بدگمانیوں کا جواب ملائمت سے دیتی۔ لیکن جب بیگم زیادہ تیز ہو جاتیں، تو ہ بھی کڑی پڑ جاتی تھی۔ قسمیں کھاتی، صفائی کی شہادتیں پیش کرتی۔ تردید اور حجت میں گھنٹوں لگ جاتے۔ قریب قریب روزانہ یہی کیفیت رہتی تھی اور روز یہ ڈراما دایہ کی خفیف سی اشک ریزی کے بعد ختم ہو جاتا تھا۔ دایہ کا اتنی سختیاں جھیل کر پڑے رہنا شاکرہ کے شکوک کی آب ریزی کرتا تھا۔ اسے کبھی یقین نہ آتا تھا کہ یہ بڑھیا محض بچے کی محبت سے پڑی ہوئی ہے۔ وہ دایہ کو ایسے لطیف جذبہ کا اہل نہیں سمجھتی تھی۔
اتفاق سے ایک روز دایہ کوبازار سے لوٹنے میں ذرا دیر ہو گئی۔ وہاں دو کنجڑنوں میں بڑے جوش و خروش سے مناظرہ تھا۔ ان کا مصور طرز ادا۔ ان کا اشتعال انگیز استدلال۔ ان کی متشکل تضحیک۔ ان کی روشن شہادتیں اور منور روائتیں ان کی تعریض اور تردید سب بے مثال تھیں۔ زہر کے دو دریا تھے۔ یا دو شعلے جو دونوں طرف سے امڈ کر باہم گتھ گئے تھے۔ کیا روانی زبان تھی۔ گویا کوزے میں دریا بھرا ہوا۔ ان کا جوش اظہار ایک دوسرے کے بیانات کو سننے کی اجازت نہ دیتا تھا۔ ان کے الفاظ کی ایسی رنگینی، تخیل کی ایسی نوعیت، اسلوب کی ایسی جدت، مضامین کی ایسی آمد، تشبیہات کی ایسی موزونیت اور فکر کی ایسی پرواز پر ایسا کون سا شاعر ہے جو رشک نہ کرتا۔ صفت یہ تھی کہ اس مباحثہ میں تلخی یا دلازاری کا شائبہ بھی نہ تھا۔ دونوں بلبلیں اپنے اپنے ترانوں میں محو تھیں۔ ان کی متانت، ان کا ضبط، ان کا اطمینان قلب حیرت انگیز تھا ۔ان کے ظرف دل میں اس سے کہیں زیادہ کہنے کی اور بدر جہا زیادہ سننے کی گنجائش معلوم ہوتی تھی۔ الغرض یہ خالص دماغی، ذہنی مناظرہ تھا۔ اپنے اپنے کمالات کے اظہار کے لیے۔ ایک خالص زور آزمائی تھی اپنے اپنے کرتب اور فن کےجوہر دکھا نے کےلیے۔
تماشائیوں کا ہجوم تھا۔ وہ مبتذل کنایات و اشارے جن پر بے شرمی کوشرم آتی۔ وہ کلمات رکیک جن سے عفونت بھی دور بھاگتی۔ ہزاروں رنگین مزاجوں کے لیے محض باعث تفریح تھے۔
دایہ بھی کھڑی ہوگئی کہ دیکھوں کیا ماجرا ہے۔ پر تماشا اتنا دلاویز تھا کہ اسے وقت کا مطلق احساس نہ ہوا۔ یکا یک نو بجنے کی آواز کان میں آئی تو سحر ٹوٹا۔ وہ لپکی ہوئی گھر کی طرف چلی۔
شاکرہ بھری بیٹھی تھی۔ دایہ کو دیکھتے ہی تیور بدل کر بولی، کیا بازار میں کھو گئی تھیں؟ دایہ نے خطا وارانہ انداز سے سرجھکا لیا اور بولی، ’’بیوی ایک جان پہچان کی ماما سے ملاقات ہوگئی اور باتیں کرنے لگی۔‘‘
شاکرہ جواب سے اور بھی برہم ہوئی۔ یہاں دفتر جانے کو دیر ہو رہی ہے تمہیں سیر سپاٹے کی سوجھی ہے۔ مگر دایہ نے اس وقت دبنے میں خیریت سمجھی۔ بچہ کو گود میں لینے چلی۔ پرشاکرہ نے جھڑک کرکہا، ’’رہنے دو۔ تمہارے بغیر بے حال نہیں ہوا جاتا۔‘‘
دایہ نے اس حکم کی تعمیل ضروری نہ سمجھی۔ بیگم صاحبہ کا غصہ فرو کرنے کی اس سے زیادہ کار گر کوئی تدبیر ذہن میں نہ آئی۔ اس نے نصیر کو اشارے سے اپنی طرف بلایا۔ وہ دونوں ہاتھ پھیلائے لڑکھڑاتا ہوا اس کی طرف چلا۔ دایہ نے اسے گود میں اٹھالیا اور دروازہ کی طرف چلی۔ لیکن شاکرہ باز کی طرح جھپٹی اور نصیر کو اس کی گود سے چھین کر بولی، ’’تمہارا یہ مکر بہت دونوں سے دیکھ رہی ہوں۔ یہ تماشے کسی اور کو دکھائیے۔ یہاں طبیعت سیر ہو گئی۔‘‘
دایہ نصیر پر جان دیتی تھی اور سمجھتی تھی کہ شاکرہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس کی سمجھ میں شاکرہ اور اس کے درمیان یہ ایسا مضبوط تعلق تھا جسے معمولی ترشیاں کمزور نہ کر سکتی تھیں۔ اسی وجہ سے باوجود شاکرہ کی سخت زبانیوں کے اسے یقین نہ آتا تھا کہ وہ واقعی مجھے نکالنے پر آمادہ ہے۔ پرشاکرہ نے یہ باتیں کچھ اس بے رخی سے کیں اور بالخصوص نصیر کو اس بے دردی سے چھین لیا کہ دایہ سے ضبط نہ ہو سکا۔ بولی، ’’بیوی مجھ سے کوئی ایسی بڑی خطا تو نہیں ہوئی۔ بہت ہو گا تو پاؤ گھنٹہ کی دیر ہوئی ہو گی۔ اس پرآپ اتنا جھلا رہی ہیں۔ صاف صاف کیوں نہیں کہہ دے تیں کہ دوسرا دروازہ دیکھو۔ اللہ نے پیدا کیا ہے تو رزق بھی دے گا۔ مزدوری کا کال تھوڑا ہی ہے۔‘‘
شاکرہ: ’’تو یہاں تمہاری کون پروا کرتا ہے۔ تمہاری جیسی مامائیں گلی گلی ٹھوکریں کھاتی پھرتی ہیں۔‘‘
دایہ: ’’ہاں خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مامائیں دائیاں بہت ملیں گی۔ جو کچھ خطا ہوئی ہو۔ معاف کیجئے گا۔ میں جاتی ہوں۔‘‘
شاکرہ: ’’جاکر مردانے میں اپنی تنخواہ کا حساب کرلو۔‘‘
دایہ: ’’میری طرف سے نصیر میاں کو اس کی مٹھائیاں منگوا دیجئے گا۔‘‘
اتنے میں صابر حسین بھی باہر سے آگئے۔ پوچھا، ’’کیا ہے؟‘‘
دایہ: ’’کچھ نہیں۔ بیوی نے جواب دے دیا ہے۔ گھر جاتی ہوں۔‘‘
صابر حسین خانگی تردات سے یوں بچتے تھے جیسے کوئی برہنہ پا کانٹوں سے بچے۔ انہیں سارے دن ایک ہی جگہ کھڑے رہنا منظور تھا۔ پرکانٹوں میں پیر رکھنے کی جرأت نہ تھی۔ چیں بہ جبیں ہو کر بولے، ’’بات کیا ہوئی؟‘‘
شاکرہ: ’’کچھ نہیں۔ اپنی طبیعت۔ نہیں جی چاہتا نہیں رکھتے۔ کسی کے ہاتھوں بک تو نہیں گئے۔‘‘
صابر: ’’تمہیں بیٹھے بٹھائے ایک نہ ایک نہ ایک کھچڑی سوجھتی رہتی ہے۔‘‘
شاکرہ: ’’ہاں مجھے تو اس بات کا جنون ہے۔ کیا کروں خصلت ہی ایسی ہے تمہیں یہ بہت پیاری ہے۔ تو لے جاکر گلے باندھو! میرے یہاں ضرورت نہیں ہے۔‘‘
دایہ گھر سے نکلی۔ تو اس کی آنکھیں لبریز تھیں۔ دل نصیر کے لیے تڑپ رہا تھا کہ ایک بار بچے کو گود میں لے کر پیار کرلوں۔ پر یہ حسرت لیے اسے گھر سے نکلنا پڑا۔ نصیر دایہ کے پیچھے پیچھے دروازے تک آیا۔ لیکن جب دایہ نے دروازہ باہر سے بند کردیا تو مچل کر زمین پر لیٹ گیا اور انا انا کہہ کر رونے لگا۔ شاکرہ نے چمکارا، پیار کیا، گود میں لینے کی کوشش کی۔ مٹھائی کا لالچ دیا۔ میلہ دکھانے کا وعدہ کیا۔ اس سے کام نہ چلا تو بندر اور سپاہی اور لولو اور ہوا کی دھمکی دی۔ پر نصیر پر مطلق اثر نہ ہوا۔ یہاں تک کہ شاکرہ کو غصہ آ گیا۔اس نے بچے کو وہیں چھوڑ دیا اورگھر آ کر گھر کے دھندوں میں مصروف ہو گئی۔ نصیر کا منہ اور گال لال ہو گئے۔ آنکھیں سوج گئیں۔ آخر وہ وہیں زمین پر سسکتے سسکتے سو گیا۔
شاکرہ نے سمجھا تھا تھوڑی دیر میں بچہ رو دھو کر چپ ہو جائے گا۔ پر نصیر نے جاگتے ہی پھر انا کی رٹ لگائی۔ تین بجے صابر حسین دفتر سے آئے اور بچے کی یہ حالت دیکھی تو بیوی کی طرف قہر کی نگاہوں سے دیکھ کر اسے گود میں اٹھالیا اور بہلانے لگے۔ آخر نصیر کو جب یقین ہو گیا کہ دایہ مٹھائی لینے گئی ہے تو اسے تسکین ہوئی ۔ مگر شام ہوتے ہی اس نے پھر چیخنا شروع کیا۔ ’’انا مٹھائی لائی؟‘‘
اس طرح دو تین دن گزر گئے۔ نصیر کو انا کی رٹ لگانے اور رونے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ وہ بے ضرر کتا جو ایک لمحہ کے لیے اس کی گود سے جدا نہ ہوتا تھا۔ وہ بے زبان بلی جسے طاق پربیٹھے دیکھ کر وہ خوشی سے پھولا نہ سماتا تھا۔ وہ طائر بے پرواز جس پر وہ جان دیتا تھا۔ سب اس کی نظروں سے گر گئے۔ وہ ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا۔ انا جیسی جیتی جاگتی پیار کرنے والی، گود میں لے کر گھمانے والی، تھپک تھپک کر سلانے والی گا گا کر خوش کرنے والی چیز کی جگہ ان بے جان، بے زبان چیزوں سے پر نہ ہو سکتی تھی۔ وہ اکثر سوتے سوتے چونک پڑتا۔ اور انا انا پکار کر رونے لگتا۔ کبھی دروازہ پر جاتا اور انا انا پکار کر ہاتھوں سے اشارہ کرتا۔ گویا اسے بلا رہا ہے۔ انا کی خالی کوٹھڑی میں جا کر گھنٹوں بیٹھا رہتا۔ اسے امید ہوتی تھی کہ انا یہاں آتی ہوگی۔
اس کوٹھڑی کا دروازہ بند پاتا تو جا کر کواڑ کھٹکھٹاتا کہ شاید انا اندر چھپی بیٹھی ہو۔ صدر دروازہ کھلتے سنتا تو انا انا کہہ کر دوڑتا۔ سمجھتا کہ انا آگئی۔ اس کا گدرایا ہوا بدن گھل گیا۔ گلاب کے سے رخسار سوکھ گئے۔ ماں اور باپ دونو ں اس کی موہنی ہنسی کے لیے ترس ترس کر رہ جاتے۔ اگر بہت گد گدانے اور چھیڑنے سے ہنستا بھی تو ایسا معلوم ہوتا دل سے نہیں محض دل رکھنے کے لیے ہنس رہا ہے۔ اسے اب دودھ سے رغبت تھی نہ مصری سے۔ نہ میوہ سے نہ میٹھے بسکٹ سے۔ نہ تازی امرتیوں سے۔ ان میں مزہ تھا جب انا اپنے ہاتھوں سےکھلاتی تھی۔ اب ان میں مزہ نہ تھا۔ دو سال کا ہونہار لہلہاتا ہوا شاداب پودا مرجھا کر رہ گیا۔ وہ لڑکا جسے گود میں اٹھاتے ہی نرمی گرمی اور زبان کا احساس ہوتا تھا۔ اب استخواں کا ایک پتلا رہ گیا تھا۔ شاکرہ بچہ کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر کڑھتی اور اپنی حماقت پر پچھتاتی۔ صابرحسین جو فطرتاً خلوت پسند آدمی تھے اب نصیر کو گود سے جدا نہ کرتے تھے۔ اسے روز ہوا کھلانے جاتے۔ نت نئے کھلونے لاتے۔ پر مرجھایا ہوا پودا کسی طرح نہ پنپتا تھا۔ دایہ اس کی دنیا کا آفتاب تھی۔ اس قدرتی حرارت اور روشنی سے محروم ہو کر سبزی کی بہار کیونکر دکھاتا؟ دایہ کے بغیر اسے چاروں طرف اندھیرا سناٹا نظر آتا تھا۔ دوسری انا تیسرے ہی دن رکھ لی تھی۔ پر نصیر اس کی صورت دیکھتے ہی منہ چھپالیتا تھا۔ گویا وہ کوئی دیونی یا بھتنی ہے۔
عالم وجود میں دایہ کو نہ دیکھ کر نصیر اب زیادہ تر عالم خیال میں رہتا۔ وہاں اس کی اپنی انا چلتی پھرتی نظر آتی تھی۔ اس کی وہی گود تھی۔ وہی محبت۔ وہی پیاری باتیں۔ وہی پیارے پیارے گیت۔ وہی مزے دار مٹھائیاں۔ وہی سہانا سنسار وہی دل کش لیل و نہار۔ اکیلے بیٹھے انا سے باتیں کرتا۔ انا کتا بھونکے، انا گائے دودھ دیتی۔ انا اجلا اجلا گھوڑا دوڑتا۔ سویرا ہوتے ہی لوٹا لے کر دایہ کی کوٹھڑی میں جاتا، اور کہتا، ’’انا پانی پی‘‘ دودھ کا گلاس لے کر اس کی کوٹھڑی میں رکھ آتا اور کہتا، ’’انا دودھ پلا۔‘‘ اپنی چار پائی پر تکیہ رکھ کر چادر سے ڈھانک دیتا اور کہتا، ’’انا سوتی۔‘‘ شاکرہ کھانے بیٹھتی تو رکابیاں اٹھا اٹھا انا کی کوٹھڑی میں لے جاتا اور کہتا، ’’انا کھانا کھائے گی۔‘‘ انا اس کے لیے اب ایک آسمانی وجود تھی۔ جس کی واپسی کی اسے مطلق امید نہ تھی۔ وہ محض گذشتہ خوشیوں کی دل کش یاد گار تھی۔ جس کی یاد ہی اس کا سب کچھ تھی۔ نصیر کے انداز میں رفتہ رفتہ طفلانہ شوخی اور بے تابی کی جگہ ایک حسرت ناک تو کل ایک مایوسانہ خوشی نظر آنے لگی۔ اس طرح تین ہفتے گزر گئے۔ برسات کاموسم تھا۔ کبھی شدت کی گرمی۔ کبھی ہوا کے ٹھنڈے جھونکے۔ بخار اور زکام کا زور تھا۔ نصیر کی نجافت ان موسمی تغیرات کو برداشت نہ کر سکی۔ شاکرہ احتیاطاً اسے فلا لین کا کرتا پہنائے رکھتی۔ اسے پانی کے قریب نہ جانے دیتی۔ ننگے پاؤں ایک قدم نہ چلنے دیتی۔ مگر رطوبت کا اثر ہو ہی گیا۔ نصیرکھانسی میں مبتلا ہو گیا۔
صبح کا وقت تھا۔ نصیر چار پائی پر آنکھیں بند کئے پڑا تھا۔ ڈاکٹروں کا علاج بے سود ہو رہا تھا۔ شاکرہ چار پائی پر بیٹھی اس کے سینہ پر تیل کی مالش کر رہی تھی اور صابر حسین صورت غم بنے ہوئے بچہ کو پردرد نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ اس طرف وہ شاکرہ سے بہت کم بولتے تھے۔ انہیں اس سے ایک نفرت سی ہوتی تھی۔ وہ نصیر کی اس بیماری کا سارا الزام اسی کے سر رکھتے تھے۔ وہ ان کی نگاہوں میں نہایت کم ظرف سفلہ مزاج بے حس عورت تھی۔
شاکرہ نے ڈرتے ڈرتے کہا، ’’آج بڑے حکیم صاحب کو بلالیتے۔ شاید انہیں کی دوا سے فائدہ ہو۔‘‘
صابر حسین نے کالی گھٹاؤں کی طرف دیکھ کر ترشی سے جواب دیا، ’’بڑے حکیم نہیں۔ لقمان بھی آئیں تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔‘‘
شاکرہ: ’’تو کیا اب کسی کی دوا ہی نہ ہوگی؟‘‘
صابر: ’’بس اس کی ایک ہی دواہے اور وہ نایاب ہے۔‘‘
شاکرہ: ’’تمہیں تو وہی دھن سوار ہے۔ کیا عباسی امرت پلادے گی؟‘‘
صابر: ’’ہاں وہ تمہارے لیے چاہے زہر ہو۔ لیکن بچے کے لیے امرت ہی ہوگی۔‘‘
شاکرہ: ’’میں نہیں سمجھتی کہ اللہ کی مرضی میں اسے اتنا دخل ہے۔‘‘
صابر: ’’اگر نہیں سمجھتی ہو اور اب تک نہیں سمجھا تو روؤگی۔ بچے سےہاتھ دھونا پڑے گا۔‘‘
شاکرہ: ’’چپ بھی رہو۔ کیسا شگون زبان سے نکالتے ہو۔ اگر ایسی جلی کٹی سنانی ہیں تو یہاں سے چلے جا ؤ۔‘‘
صابر: ’’ہاں تو میں جاتا ہوں۔ مگر یاد رکھو یہ خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ اگر لڑکے کو پھر تندرست دیکھنا چاہتی ہو تو ا س عباسی کے پاس جاؤ۔ اس کی منت کرو، التجا کرو۔ تمہارے بچے کی جان اسی کے رحم پر منحصر ہے۔‘‘
شاکرہ نے کچھ جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔
صابر حسین نے پوچھا، ’’کیا مرضی ہے۔ جاؤں اسے تلاش کروں؟‘‘
شاکرہ: ’’تم کیوں جاؤ گے۔ میں خود چلی جاؤں گی۔‘‘
صابر: ’’نہیں۔ معاف کرو۔ مجھے تمہارے اوپر اعتبار نہیں ہے۔ نہ جانے تمہارے منہ سے کیا نکل جائے کہ وہ آتی بھی ہو تو نہ آئے۔‘‘
شاکرہ نےشوہر کی طرف نگاہ ملامت سے دیکھ کر کہا۔’’ہاں اور کیا۔ مجھے اپنے بچے کی بیماری کا قلق تھوڑے ہی ہے۔ میں نے شرم کے مارے تم سے کہا نہیں لیکن میرے دل میں بار بار یہ خیال پیدا ہوا ہے اگر مجھے دایہ کے مکان کا پتہ معلوم ہوتا تو میں اسے کب کی منا لائی ہوتی۔ وہ مجھ سےکتنی ہی ناراض ہو لیکن نصیر سے اسے محبت تھی۔ میں آج ہی اس کے پاس جاؤں گی۔ اس کے قدموں کو آنسوؤں سے تر کر دوں گی اور وہ جس طرح راضی ہو گی اسے راضی کروں گی۔‘‘
شاکرہ نے بہت ضبط کر کے یہ باتیں کہیں۔ مگر امڈے ہوئے آنسو اب نہ رک سکے۔ صابر حسین نے بیوی کی طرف ہمدردانہ نگاہ سے دیکھا اور نادم ہو کر بولے، ’’میں تمہارا جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ میں خود ہی جاتا ہوں۔‘‘
عباسی دنیا میں اکیلی تھی۔کسی زمانے میں اس کا خاندان گلاب کا سر سبز شاداب درخت تھا۔ مگر رفتہ رفتہ خزاں نے سب پتیاں گرادیں۔ بادحوادث نے درخت کو پامال کردیا۔ اور اب یہی سوکھی ٹہنی ہرے بھرے درخت کی یادگار باقی تھی۔مگر نصیر کو پاکر اس کی سوکھی ٹہنی میں جان سی پڑ گئی تھی۔ اس میں ہری پتیاں نکل آئی تھیں۔ وہ زندگی جو اب تک خشک اور پامال تھی اس میں پھر رنگ و بو کے آثار پیدا ہوگئے تھے۔ اندھیرے بیابان میں بھٹکے ہوئے مسافر کو شمع کی جھلک نظر آنے لگی تھی۔ اب اس کا جوئے حیات سنگ ریزوں سے نہ ٹکراتا تھا وہ اب ایک گلزار کی آبیاری کرتا تھا۔ اب اس کی زندگی مہمل نہیں تھی۔ اس میں معنی پید اہو گئے تھے۔
عباسی، نصیر کی بھولی باتوں پر نثار ہو گئی۔ مگر وہ اپنی محبت کو شاکرہ سے چھپاتی تھی۔ اس لیے کہ ماں کے دل میں رشک نہ ہو۔ وہ نصیر کے لیے ماں سے چھپ کر مٹھائیاں لاتی اور اسے کھلا کر خوش ہوتی۔ وہ دن میں دودو تین تین بار اسے ابٹن ملتی کہ بچہ خوب پروان چڑھے۔ وہ اسے دوسروں کے سامنے کوئی چیز نہ کھلاتی کہ بچے کو نظر نہ لگ جائے۔ ہمیشہ دوسروں سے بچے کی کم خوری کا رونا رویا کرتی۔ اسے نظر بد سے بچانے کے لیے تعویز اور گنڈے لاتی رہتی یہ اس کی خالص مادرانہ محبت تھی۔ جس میں اپنے روحانی احتظاظ کے سوا اور کوئی غرض نہ تھی۔
اس گھر سے نکل کر آج عباسی کی وہ حالت ہو گئی جو تھیٹر میں یکا یک بجلیوں کے گل ہو جانے سے ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہی صورت ناچ رہی تھی۔ کانوں میں وہی پیاری پیاری باتیں گونج رہی تھیں۔ اسے اپنا گھر پھاڑے کھاتا تھا۔ اس کال کوٹھڑی میں دم گھٹا جاتا تھا۔
رات جوں توں کرکے کٹی۔ صبح کو وہ مکان میں جھاڑو دے رہی تھی۔ یکایک تازے حلوے کی صدا سن کر بے اختیار باہر نکل آئی۔ معاً یاد آگیا۔ آج حلوہ کون کھائے گا؟ آج گود میں بیٹھ کر کون چہکے گا؟ وہ نغمہ مسرت سننے کے لیے جو حلوا کھاتے وقت نصیر کی آنکھوں سے، ہونٹوں سے اور جسم کے ایک ایک عضو سے برستا تھا۔ عباسی کی روح تڑپ اٹھی۔ وہ بے قراری کے عالم میں گھر سے نکلی کہ چلوں نصیر کو دیکھ آؤں۔ پر آدھے راستہ سے لوٹ گئی۔
نصیر عباسی کے دھیان سے ایک لمحہ کے لیے بھی نہیں اترتا تھا۔ وہ سوتے سوتے چونک پڑتی۔ معلوم ہوتا، نصیر ڈنڈے کا گھوڑا دبائے چلا آتا ہے۔ پڑوسنوں کے پاس جاتی تو نصیر ہی کا چرچا کرتی۔ اس کے گھر کوئی آتا تو نصیر ہی کا ذکر کرتی۔ نصیر اس کے دل اور جان میں بسا ہوا تھا۔ شاکرہ کی بے رخی اور بدسلوکی کے ملال کے لیے اس میں جگہ نہ تھی۔
وہ روز ارادہ کرتی کہ آج نصیر کو دیکھنے جاؤں گی۔ اس کے لیے بازار سےکھلونے اور مٹھائیاں لاتی۔ گھر سے چلتی۔ لیکن کبھی آدھے راستہ سے لوٹ آتی۔ کبھی دو چار قدم سے آگے نہ بڑھا جاتا۔ کون منہ لے کر جاؤں؟ جو محبت کو فریب سمجھتا ہو، اسے کون منہ دکھاؤں۔ کبھی سوچتی کہیں نصیر مجھے نہ پہچانےتو بچوں کی محبت کا اعتبار؟ نئی دایہ سے پرچ گیا ہو۔ یہ خیال اس کے پیروں پر زنجیر کا کام کر جاتا تھا۔
اس طرح دو ہفتے گزر گئے۔ عباسی کا دل ہر دم اچاٹ رہتا۔ جیسے اسے کوئی لمبا سفر درپیش ہو۔ گھر کی چیزیں جہاں کی تہاں پڑی رہتیں۔ نہ کھانے کی فکر نہ کپڑے کی۔ بدنی ضروریات بھی خلاء دل کو پر کرنے میں لگی ہوئی تھیں۔ عباسی کی حالت اس وقت پالتو چڑیا کی سی تھی جو قفس سے نکل کر پھر کسی گوشہ کی تلاش میں ہو۔ اسے اپنے تئیں بھلا دینے کا یہ ایک بہانہ مل گیا۔ آمادہ سفر ہوگئی۔
آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی ہوئی تھیں اور ہلکی ہلکی پھواریں پڑ رہی تھیں۔ دہلی اسٹیشن پر زائرین کا ہجوم تھا۔ کچھ گاڑیوں میں بیٹھے تھے، کچھ اپنے گھر والوں سے رخصت ہو رہے تھے۔ چاروں طرف ایک کہرام سا مچا ہوا تھا۔ دنیا اس وقت بھی جانے والوں کے دامن پکڑے ہوئے تھی۔ کوئی بیوی سے تاکید کر رہا تھا۔ دھان کٹ جائے تو تالاب والے کھیت میں مٹر بو دینا اور باغ کے پاس گیہوں۔ کوئی اپنے جوان لڑکے کو سمجھا رہا تھا۔ اسامیوں پر بقایا لگان کی نالش کرنے میں دیر نہ کرنا اور دو روپیہ سیکڑہ سود ضرور مجرا کر لینا۔ ایک بوڑھے تاجر صاحب اپنے منیم سے کہہ رہے تھے۔ مال آنے میں دیر ہو تو خود چلے جائیے گا اور چلتو مال لیجیے گا۔ ورنہ روپیہ پھنس جائے گا۔ مگر خال خال ایسی صورتیں بھی نظر آتی تھیں جن پر مذہبی ارادت کا جلوہ تھا۔
وہ یا تو خاموش آسمان کی طرف تاکتی تھیں یا محو تسبیح خوانی تھیں۔ عباسی بھی ایک گاڑی میں بیٹھی سوچ رہی تھی۔ ان بھلے آدمیوں کو اب بھی دنیا کی فکر نہیں چھوڑتی۔ وہی خرید و فروخت لین دین کے چرچے نصیر اس وقت یہاں ہو تا تو بہت روتا۔ میری گود سے کسی طرح نہ اترتا۔ لوٹ کر ضرور اسے دیکھنے جاؤں گی۔ یااللہ کسی طرح گاڑی چلے۔ گرمی کے مارے کلیجہ بھنا جاتا ہے۔ اتنی گھٹا امڈی ہوئی ہے۔ برسنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ معلوم نہیں یہ ریل والے کیوں دیر کر رہے ہیں؟ جھوٹ موٹ ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں یہ نہیں کہ چٹ پٹ گاڑی کھول دیں۔ مسافروں کی جان میں جان آئے۔ یکا یک اس نے صابر حسین کو بائیسکل لیے پلیٹ فارم پر آتے دیکھا۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور کپڑے تر تھے۔ وہ گاڑیوں میں جھانکنے لگے۔ عباسی محض یہ دکھانے کے لیے کہ میں بھی حج کرنے جارہی ہوں۔ گاڑی سے باہر نکل آئی۔ صابر حسین اسے دیکھتے ہی لپک کر قریب آئے اور بولے، ’’کیوں عباسی تم بھی حج کو چلیں؟‘‘
عباسی نے فخریہ انکسار سے کہا، ’’ہاں! یہاں کیا کروں؟ زندگی کا کوئی ٹھکانا نہیں۔ معلوم نہیں کب آنکھیں بند ہو جائیں۔ خدا کے یہاں منہ دکھانے کے لیے بھی تو کوئی سامان چاہیئے۔ نصیر میاں تو اچھی طرح ہیں؟‘‘
صابر: ’’اب تو تم جاری ہو۔ نصیر کا حال پوچھ کر کیا کرو گی۔ اس کے لیے دعا کرتی رہنا۔‘‘
عباسی کا سینہ دھڑکنے لگا۔ گھبرا کر بولی، ’’کیا دشمنوں کی طبیعت اچھی نہیں ہے؟‘‘
صابر: ’’اس کی طبیعت تو اسی دن سے خراب ہے جس دن تم وہاں سے نکلیں۔ کوئی دوہفتہ تک تو شب روز انا انا کی رٹ لگا تا رہا۔ اور اب ایک ہفتہ سے کھانسی اور بخار میں مبتلا ہے۔ ساری دوائیں کر کے ہار گیا۔ کوئی نفع ہی نہیں ہوتا۔ میں نے ارادہ کیاتھا۔ چل کر تمہاری منت سماجت کر کے لے چلوں۔ کیا جانے تمہیں دیکھ کر ا س کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ لیکن تمہارے گھر پر آیا۔ تو معلوم ہوا کہ تم حج کرنے جارہی ہو۔ اب کس منہ سے چلنے کو کہوں۔ تمہارے ساتھ سلوک ہی کون سا اچھا کیا تھا کہ اتنی جرأت کر سکوں اور پھر کار ثواب میں رخنہ ڈالنے کا بھی خیال ہے۔ جاؤ! اس کا خدا حافظ ہے۔ حیات باقی ہے تو صحت ہو ہی جائے گی۔ ورنہ مشیت ایزدی سےکیا چارہ؟‘‘
عباسی کی آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ سامنے چیزیں تیرتی ہوئی معلوم ہوئیں۔ دل پر ایک عجیب وحشت کا غلبہ ہوا۔ دل سے دعا نکلی۔ ’’اللہ میری جان کے صدقے۔ میرے نصیر کا بال بیکا نہ ہو۔‘‘ رقت سے گلا بھر آیا۔ میں کیسی سنگ دل ہوں۔ پیارا بچہ رو رو کر ہلکان ہو گیا اور اسے دیکھنے تک نہ گئی۔ شاکرہ بدمزاج سہی، بدزبان سہی۔ نصیر نے میرا کیا بگاڑا تھا؟ میں نے ماں کا بدلہ نصیر سے لیا۔ یا خدا میرا گناہ بخشیو! پیارا نصیر میرے لیے ہڑک رہا ہے (اس خیال سے عباسی کا کلیجہ مسوس اٹھا اور آنکھوں سے آنسو بہ نکلے) مجھے کیا معلوم تھا کہ اسے مجھ سے اتنی محبت ہے۔ ورنہ شاکرہ کی جوتیاں کھاتیں اور گھر سے قدم نہ نکالتی۔ آہ! نہ معلوم بچارے کی کیا حالت ہے؟ انداز وحشت میں بولی، ’’دودھ تو پیتے ہیں نا؟‘‘
صابر: ’’تم دودھ پینے کو کہتی ہو۔ اس نے دو دن سے آنکھیں تو کھولیں نہیں۔‘‘
عباسی: ’’یا میرے اللہ! ارے او قلی ،قلی! بیٹا! آ کے میرا اسباب گاڑی سے اتار دے۔ اب مجھے حج وج کی نہیں سوجھتی۔ ہاں بیٹا! جلدی کر۔ میاں دیکھئے کوئی یکہ ہو تو ٹھیک کر لیجیے!‘‘
یکہ روانہ ہوا۔ سامنے سڑک پر کئی بگھیاں کھڑی تھیں۔ گھوڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ عباسی بار بار جھنجلاتی تھی اور یکہ بان سے کہتی تھی، ’’بیٹا جلدی کر! میں تجھے کچھ زیادہ دے دوں گی۔‘‘ راستے میں مسافروں کی بھیڑ دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا اس کا جی چاہتا تھا گھوڑے کے پر لگ جاتے۔ لیکن جب صابر حسین کا مکان قریب آ گیا تو عباسی کا سینہ زور سے اچھلنے لگا۔ بار بار دل سے دعاء نکلنے لگی۔ خدا کرے۔ سب خیرو عافیت ہو۔
یکہ صابر حسین کی گلی میں داخل ہوا۔ دفعتہً عباسی کو رونے کی آواز آئی۔ اس کا کلیجہ منہ کو آگیا۔ سر تیورا گیا،معلوم ہوا۔ دریا میں ڈوبی جاتی ہوں جی چاہا یکہ سے کود پڑوں۔ مگر ذرا دیر میں معلوم ہوا کو عورت میکہ سے بدا ہو رہی ہے۔ تسکین ہوئی۔
آخر صابر حسین کا مکان آ پہنچا۔ عباسی نے ڈرتے ڈرے دروازے کی طرف تاکا۔ جیسے کوئی گھر سے بھاگا ہوا یتیم لڑکا شام کو بھوکا پیاسا گھر آئے۔ اور دروازے کی طرف سہمی ہوئی نگاہ سے دیکھے کہ کوئی بیٹھا تو نہیں ہے۔ دروازہ پرسناٹا چھایا ہوا تھا۔ باورچی بیٹھا حقہ پی رہا تھا۔ عباسی کو ذرا ڈھارس ہوئی۔ گھر میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ نئی دایہ بیٹھی پولٹس پکا رہی ہے۔ کلیجہ مضبوط ہوا۔ شاکرہ کے کمرے میں گئی تو اس کا دل گرما کی دوپہری دھوپ کی طرح کانپ رہا تھا۔ شاکرہ نصیر کو گود میں لیے دروازے کی طرف ٹکٹکی لگائے تاک رہی تھی۔ غم اور یاس کی زندہ تصویر۔
عباسی نے شاکرہ سے کچھ نہیں پوچھا۔ نصیر کو اس کی گود سے لے لیا۔ اور اس کے منہ کی طرف چشم پرنم سے دیکھ کر کہا، ’’بیٹا! نصیر آنکھیں کھولو۔‘‘
نصیر نے آنکھیں کھولیں۔ ایک لمحہ تک دایہ کو خاموش دیکھتا رہا۔ تب یکا یک دایہ کے گلے سے لپٹ گیا اور بولا، ’’انا آئی۔ انا آئی۔‘‘ نصیر کا زرد مرجھایا ہوا چہرہ روشن ہو گیا۔ جیسے بجھتے ہوئے چراغ میں تیل جائے۔ ایسا معلوم ہوا گویا وہ کچھ بڑھ گیا ہے۔
ایک ہفتہ گزر گیا۔ صبح کا وقت تھا۔ نصیر آنگن میں کھیل رہا تھا۔ صابر حسین نے آکر اسے گود میں اٹھالیا اور پیار کر کے بولے۔’’تمہاری انا کو مار کر بھگا دیں؟‘‘
نصیر نے منہ بنا کر کہا، ’’نہیں روئے گی۔‘‘
عباسی بولی، ’’کیوں بیٹا! مجھے تو تو نے کعبہ شریف نہ جانے دیا۔ میرے حج کا ثواب کون دے گا؟‘‘
صابر حسین نے مسکرا کر کہا، ’’تمہیں اس سے کہیں زیادہ ثواب ہو گیا۔ اس حج کا نام حج اکبر ہے۔‘‘




