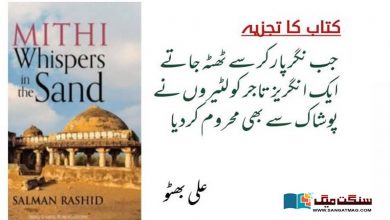یہ چھ فیٹ کشادہ ایک گلی ہے، بالکل پختہ، جس میں داخل ہوتے ہی ایک ٹیوب ویل سے ٹکرانا پڑتا ہے جو اب کام نہیں کرتا۔ یہ گلی سرخ پرچم کا ایک ناقابلِ شکست گڑھ ہے۔ الیکشن کے دنوں میں یا پارٹی کی برسی کے موقعے پر یا کسی بڑے نیتا کی آمد پر اکثر اس پر ایک سرخ جھنڈا لہرا دیا جاتا ہے جو اپنی درانتی اور ہتھوڑے کا بوجھ شاید سنبھال نہ پانے کے سبب زیادہ تر اپنے پتلے بانس پر گرا رہتا ہے۔
ایک دن میں اسے کام کے لائق بنانے کا بیڑا اٹھاتا ہوں اور چونکہ میں نے اتنے بڑے کام کا تہیہ کیا ہے، تھوڑا بہت میرے بارے میں بھی۔۔
میں اس گلی میں رہتا ہوں۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ یہ گلی میرے اندر رہتی ہے۔ ہمارے مکان کے صدر دروازے پر لوہے کے دو کڑے دیوار سے لٹک رہے ہیں جو اس بات کا غماز ہے کہ کبھی ان سے گھوڑے باندھے جاتے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی پرانا مکان ہے، بہت ہی خستہ حال، جس کی دیواروں کے کارنس پر کبوتروں نے ٹھکانہ بنا رکھا ہے۔ ان کی آوازیں عموماً صبح کے وقت گونجا کرتی ہیں، باقی وقتوں میں یہ اپنے سَروں کو جسموں کے اندر چھپائے دنیا و مافیہا سے بے خبر رہتے ہیں یا بلا وجہ پاس پڑوس کی چھتوں کے اوپر چکر لگاتے نظر آتے ہیں۔ مجھے کبوتر اچھے نہیں لگتے۔ یہ پوری گلی کو گندا کرتے رہتے ہیں، خاص طور پر موسمِ سرما میں۔ ایک بار ایک کبوتر کے مردہ جسم کو میں نے گلی میں دیکھا تھا، اسے ایک بلّی نوچ رہی تھی۔ میں نے بلی کو بھگا تو دیا مگر میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اب اس نِچے نچائے کبوتر کا کیا کروں۔ اس شام جب میں آفس سے گھر لوٹا تو میں نے دیکھا گلی میں کبوتر اپنی جگہ اسی طرح اپنے پنجوں کو اوپر اٹھائے پڑا تھا۔ صرف اس کی دونوں آنکھیں کالی چینٹیوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ دیر تک اپنے دروازے پر کھڑا میں اسے تاکتا رہا، یہاں تک کہ دروازے کے اوپر کی قد آدم کھڑکی کھل گئی اور مجھے اپنی بیوی بندنا کی آواز سنائی دی۔
’’اب اندر آ بھی جاؤ، باہر کتنی شبنم ہے۔‘‘
باہر کتنی شبنم ہے۔۔ میں اپنی ہتھیلی کو سر پر رکھ کر دیکھتا ہوں، میرے بال واقعی گیلے ہو رہے ہیں۔ پہلی بار مجھے ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے اور میں گھر کے اندر داخل ہوتا ہوں۔ نیچے کا صحن حمّام کے طور پر استعمال ہوتا ہے جو کرایہ داروں کے کپڑے دھونے اور نہانے کے سبب ہمیشہ گیلا رہتا ہے۔ اس کے حوض کے پانی میں پرندوں کی بیٹ اور پر تیرتے رہتے ہیں، کبھی کبھار کوئی مرا ہوا چوہا بھی اس سے نکال کر پھینکنا پڑتا ہے۔ دیواروں پر ایک دائمی سیلن ہے۔ ان نیم تاریک کمروں میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ اسی مکان کی طرح ہی پرانے ہیں۔ ایک بار ایک بوڑھے کو میں نے دیکھا تھا۔ وہ کھانستے ہوے میری طرف تاک رہا تھا۔
’’دادو موئے، کچھ چاہیے؟‘‘ میں نے ان سے پوچھا تھا۔
’’بھوانی شیو شنکر کے بعد یہاں ذرا بھی لوگوں کے دل میں دَیا نہیں ہے،‘‘ وہ میرے دادا کے بارے میں کہنے لگے، ’’اور تم اتنے بھی نہ تھے اور ننگے گھومتے تھے، جب میں یہاں آیا، جب ہم نے کچھ اچھے دن گزارے۔۔ لیکن کتنے دن؟ ملک آزاد ہوا اور شکرے بڑی تعداد میں آسمان پر آ گئے۔‘‘
میں نے تائید میں سر ہلایا۔ کسی غیر ضروری بحث کو روکنے کا اس سے زیادہ موثر طریقہ اور بھلا کیا ہو سکتا ہے۔۔ مگر پریمل دا سے چھٹکارا پانا کیا اتنا آسان تھا؟
’’کچھ چھ سو شکرے،‘‘ انہوں نے گنانا شروع کیا، ’’اور نوچنے والے گدھ اور چیل اور کوے اور گیدڑ، جن کے بعد کتے اور لگاتار کتے، تمام کے تمام لنڈورے اور نطفہِ نا تحقیق۔۔‘‘
وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتے تھے مگر کس کے پاس اتنی فرصت تھی۔۔ چھ سال پہلے پریمل دا کو ایک بار ہم لوگوں نے علی پور کے پاگل خانے میں بھرتی کروایا تھا۔ آج تک وہ اس کا غصّہ ہم لوگوں پر اتارا کرتے ہیں۔ سیڑھی سے اوپر جاتے ہوے میں نے دیکھا، پریمل دا اچانک چپ ہو گئے تھے اور اپنی عینک کے موٹے موٹے شیشوں کے اندر سے مجھے تاک رہے تھے۔
اوپر کے کمروں میں سے دو ہمارے حصے میں آئے تھے۔ یہاں ایک کمرے میں، میں بندنا کے ساتھ ایک اونچے پلنگ پر سوتا تھا، دوسرے کمرے میں میرے دو بچے بڑے ہو رہے تھے۔ سلاخوں والی قدآدم کھڑکیوں کے باوجود گلی کی تنگی کے سبب ان کمروں میں روشنی کا گزر کم ہوتا تھا۔ اوپر سے ہم نے ایک کتّا پال رکھا تھا، ہیرامن، جو زیادہ تر وقت اندر صحن کی طرف کھلنے والی گیلری میں، جو لوگوں کی گزر گاہ بھی تھی، اپنا چہرہ کسی فلاسفر کی طرح لٹکائے بیٹھا رہتا یا چوہوں کا پیچھا کیا کرتا؛ چوہے جو پرانے ڈرین پائپوں کے رخنوں سے نمودار ہوتے مگر انسانوں کا سایہ دیکھتے ہی جانے کہاں چھپ جاتے۔
ٹیوب ویل سے اتنی دور بھٹک جانے کا میرا مقصد اور کچھ نہیں، بلکہ اس ٹیوب ویل کے آس پاس کی دنیا کی تصویر کھینچنا تھا، تاکہ اس کی کہانی مکمل ہو سکے۔۔ ورنہ یہ نٹ بولٹ اور پائپ کا بے جان ٹکڑا اپنی کوئی کہانی بھی رکھتا ہے؟ اسے دباؤ تو یہ کراہتا ہے، لگاتار دباؤ تو یہ پانی اگل دیتا ہے۔۔ مگر اس ٹیوب ویل کی ٹونٹی تو اب کچھ بھی نہیں اگلتی، ایک بوڑھے آدمی کی طرح، جس کی شہوانی طاقت دم توڑ چکی ہو، یا کسی سالخوردہ کنواری کی طرح جو اپنی شہوانی خواہشات کا گلا دباتے دباتے ایک ٹھنٹھ میں بدل گئی ہو۔ یہ ٹیوب ویل اندر سے پوری طرح ناکارہ ہو چکا ہے۔۔ یا ہو سکتا ہے کہ پانی کا وہ زمین دوز چشمہ، جس سے یہ منسلک تھا، اپنا راستہ بدل چکا ہو۔۔ یا ہمیشہ کے لیے سوکھ چکا ہو۔ گلی کے لوگ نکڑ پر آنے والے ایک بڑے ٹینکر کا انتظار کرتے ہیں۔ کارپوریشن کا یہ ٹینکر کبھی صحیح وقت پر نہیں آتا، لیکن جب آتا ہے، اس کی ایک آنکھ والا ڈرائیور اپنی سیٹ سے اتر کر لوگوں کو اپنا گرویدہ بنانے کی کوشش میں لگ جاتا ہے، جبکہ لوگ پلاسٹک کی بالٹیاں یا پیتل کے گھڑے اٹھائے قطار باندھے دشوار گذار چہرے لیے کھڑے رہتے ہیں۔
’’ذرا سوچو، اتنا پانی ہمارے معدوں، ہماری پیشاب کی نالیوں سے گزر جاتا ہے اور ہم لوگوں کو اس کا پتا بھی نہیں چلتا۔‘‘ یہ اس کا محبوب طریقۂ کلام ہے، جسے وہ ہر بار ایک ہی انداز سے دہراتا ہے، جیسے یہ الفاظ کسی سے سن کر اس نے رٹ لیے ہوں، ’’یہ دنیا ہم انسانوں کے سبب اب رہنے کے لائق نہیں رہ گئی ہے۔ اچھا کھاؤ گندا نکالو، اچھی چیز پیو بری چیز باہر کرو، صاف ہوا اندر لو بدبو دار خارج کرو، ہم گندگی پیدا کرنے والی مشینیں ہیں۔۔‘‘
وہ واقعی ایک فلاسفر تھا!
مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ ڈرائیور ہر بار وہی آدمی نہیں نکلتا اور ایک بار تو ہم نے ایک ایسے ڈرائیور کو دیکھا، جسے کھجلی کی بیماری تھی اور جس کے چہرے کا رنگ گرا ہوا تھا اور جب لوگ ٹینکر کی ٹونٹی سے پانی بھر رہے تھے، وہ دیوار سے اپنے جسم کو رگڑ رہا تھا اور اس کا داہنا ہاتھ لگاتار اپنے فتق کو کھجائے جا رہا تھا اور جب پانی لینے والوں کی بھیڑ مفقود ہو گئی، وہ ہاتھ کے اشارے سے گویا گلی کے تمام موجود اور غیر موجود لوگوں سے مخاطب ہو گیا تھا، ’’لو دیکھو۔ پہلے تو لوگ پانی کے لیے اتنا شور مچا رہے تھے اور اب کوئی نہیں آتا۔ اب میں اس باقی پانی کا کیا کروں گا؟ اب تو کتے بھی اس میں نہانے نہیں آتے۔‘‘
واقعہ یہ تھا کہ اس وقت تک نکڑ پر جمع ہونے والے سارے کتے ٹینکر کے نیچے گرے ہوے پانی میں لوٹ پوٹ کر جا چکے ہوتے۔
اور جب ٹینکر چلا جاتا تو ایک بھکاری نمودار ہوتا اور ٹینکر کی گیلی جگہ پر اپنا کیلوں مہاسوں سے ڈھکا چہرہ لٹکا کر کھڑا ہو جاتا۔ اس کی ایک آنکھ پتھر کی تھی اور دوسری آنکھ پر موتیا بند نے تین چوتھائی سے زیادہ حملہ کر رکھا تھا۔ اس موتیا بند کے علاج کے لیے اس کے پاس یا تو پیسہ نہیں تھا یا شاید اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے سبب لوگ اس پر زیادہ ترس کھانے پر مجبور تھے۔
’’سارے رشتے من کے دھوکے،‘‘ وہ بیچ بیچ میں تکرار لگاتا، ’’دے کرشنا تو کون روکے۔‘‘
دراصل اسے دیوار گیر مندر کا پجاری مہالٹ گوسوامی کہیں سے ڈھونڈ لایا تھا اور اپنے مندر کی آمدنی بڑھانے کے لیے اس نے اسے اس جگہ لا کھڑا کیا تھا۔ اکثر دیر رات گئے ان دونوں کے جھگڑنے کی آواز محلے والے سنتے، جب وہ نشے میں دھت بھیک کے پیسے آپس میں بانٹا کرتے اور یہ معاملہ زیادہ تر ہاتھا پائی میں بدل جاتا۔
تین سو برس قبل یہ شہر سندر بن کا ہی ایک حصہ تھا۔ پھر ایک دن ایک آدمی ایک گھڑیال کے سر پر پیر رکھ کر اپنے مستولی جہاز سے نیچے اترا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، وہ افیم کے نشے میں دھت تھا اور چاروں طرف پھیلی ہریالی اور دلدلی زمین سے قدرے ہراساں نظر آ رہا تھا، جو سانپ اور کھڑیالوں سے اٹے پڑے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی اور سوچا، سارے کا سارا معاملہ ہی یہاں بے تکا ہے۔ وقت گزرتا رہا۔۔ پھر ایک دن اچانک انگریزوں نے بگل بجا کر اپنا جھنڈا واپس لپیٹ لیا اور دلی کی طرف کوچ کر گئے، جس کے بعد لوگوں نے دیکھا معاملہ کچھ اور بےتکا ہو چکا تھا۔ یا شاید جب سب کچھ ہو چکتا ہے تو بے تکا ہونے کا احساس کچھ اور زیادہ گہرا ہونے لگتا ہے۔۔ لیکن ہوگلی ندی میں پانی بھلا کب رکنے والا تھا۔ وہ بہتا رہا، دن بدن اور گدلا ہوتا رہا، فیکٹری کی چمنیاں آسمان کو داغدار کرتی رہیں، ہمارے گھر کی دیواروں سے پلستر جھڑتے رہے، کچھ لوگ کھڑکیوں پر چہرہ رکھ کر بھول گئے اور کچھ لوگ بےچہرہ ایک لمبی زندگی جی کر شمشان گھاٹ کے راستے ہو لیے اور میں، جس نے ٹیوب ویل سے پانی نکالنے کا بیڑا اٹھایا تھا، مجھے نئے سرے سے سارے معاملے کی چھان پھٹک کرنی پڑی۔ آخر مجھے دیکھنا بھی تھا، کیا میں واقعی اس کام کا اہل بھی تھا؟
کیا میں اس کام کا اہل بھی تھا؟ یہ سوال پہلی اور آخری بار میں نے خود سے کیا تھا۔ میں نے اپنے جوتوں کے تسمے باندھتے وقت لا پروائی سے سر ہلا کر ایک طرح سے اس سوال کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قلع قمع کر دیا تھا۔ میں نے اپنے بڑے لڑکے سے کہا وہ اپنی پڑھائی میں زیادہ دھیان دے کیونکہ وقت بہت برا آ گیا ہے اور اب انجینئر اور ڈاکٹر بھی بیکار گھومنے لگے ہیں۔ میرا ارادہ اس کی دل شکنی کرنے کا نہ تھا، مگر میری بیوی نے اسے پسندیدہ نظروں سے نہیں دیکھا۔
’’تمہارے آسمان پر صرف کالے بادل ہی کیوں منڈلاتے ہیں؟‘‘ اس نے مجھ سے کہا، ’’بچوں پر اس کا برا اثر پڑتا ہے۔ ان سے ہمیشہ اچھی باتیں کیا کرو۔ بچے پھول کے مانند ہوتے ہیں۔ وہ کم دھوپ میں مرجھا جاتے ہیں اور تیز دھوپ میں مر جاتے ہیں۔‘‘
’’بندنا، تم تو شاعر ہو!‘‘ میں نے مسکرا کر اس کی طرف تاکتے ہوے کہا، ’’تم کویتا کیوں نہیں لکھتیں؟ ٹاؤن ہال کے ایک کلرک سے میری پرانی پہچان ہے۔ تم وہاں کی تقریبات میں شاعرہ کے طور پر شرکت کر سکتی ہو۔ انہیں اپنی ادبی محفلوں کی شوبھا بڑھانے کے لیے زنانی شاعروں کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے۔۔ اور پھر میں تمہاری کویتاؤں کے لیے ایک ناشر ضرور ڈھونڈ لوں گا جو تمہاری کویتا کی کتاب شائع کرنے کے بعد پہلے سے کچھ اور زیادہ غریب ہو جائے گا۔ کالج اسٹریٹ میں ایک سے ایک پاگل پبلشر بھرے پڑے ہیں۔‘‘
’’کیا کویتا لکھنا اتنا آسان ہے؟‘‘ بندنا نے جواب دیا، ’’کیا آج کے آدمی کے پاس کویتا کے لیے وقت ہے بھی؟ میں پچھلے پندرہ برس سے تمہیں دیکھ رہی ہوں، میں نے تو تمہیں کبھی کویتا کی کتاب پڑھتے نہیں دیکھا، جب کہ تم ہر وقت فٹ بال کی خبروں میں مست رہتے ہو۔ تمہارے لیے تو دنیا کا مرکز موہن بگان کلب ہے۔‘‘
’’تم پریسیڈنسی کی چھاترا رہ چکی ہو نا، اس لیے مجھے تم سے ڈر لگتا ہے،‘‘ میں مسکرا کر کہتا ہوں، ’’اور دیکھو، تم مشرقی پاکستان سے بھاگ کر آئے ہوے لوگوں کی بھاشا مت بولا کرو۔‘‘
’’میں نے کب ایسٹ بنگال کلب کا سپورٹ کیا ہے؟‘‘
’’میں سب سمجھتا ہوں۔ تم ایس ایف آئی کی ممبر رہ چکی ہو اور اس میں کن لوگوں کی تعداد زیادہ ہے؟‘‘
’’تم تو بس۔۔۔‘‘ بندنا ہنس کر کہتی ہے، ’’ایسا نہیں کہ مجھے فٹ بال پسند نہیں۔ صرف اس میں مجھے دیسی اور بدیسی بنگالیوں کی بات نہیں بھاتی، جس طرح کرکٹ میں مجھے ہندوستان پاکستان والا معاملہ اچھا نہیں لگتا۔ یہاں نفرت کو حب الوطنی کا نام دے کر لوگ سینہ پھلائے گھومتے ہیں اور کھلاڑی اسی درمیان امیر سے امیر تر ہوتے جاتے ہیں۔‘‘
’’یہ ہماری نفرت ہی ہے جس کے ذریعے ہم زیادہ متحرک رہتے ہیں، بلکہ اب تو ساری دنیا کو اس کا پتا چل چکا ہے کہ یہ دنیا نفرت کے لیے کتنا اچھا بازار ہے۔ ایک لبرل کا نقاب پہن کر تم اس کی اہمیت کم نہیں کر سکتیں،‘‘ میں کہتا ہوں، ’’اور پھر ان سب کا اپنا ایک الگ مزہ ہے۔ یہ تم نہیں سمجھ سکتیں۔ تم کو تو ساری دنیا میں کہیں پر کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا، جبکہ پہاڑوں پر لوگ ناٹے ہیں اور سانپ کھاتے ہیں اور میدانوں میں لوگ زیادہ چتُر ہوتے ہیں، زیادہ بیماریوں میں مبتلا رہتے ہیں اور انہیں اخبار بینی کا شوق ہوتا ہے۔‘‘
بندنا جب ہارنے لگتی ہے تو میرے سینے سے لپٹ کر میری کھردری داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے، ’’مجھے پتا ہے تم کالج میں ڈبیٹ میں ہمیشہ اوّل آتے تھے۔۔ مگر گھر میں تو کبھی کبھار مجھے جیتنے دیا کرو۔‘‘
’’یہی تو،‘‘ میں اس کے خوبصورت بالوں میں انگلیاں ڈال کر کہتا ہوں، جن پر فدا ہوکر میں نے اس کے ساتھ سات پھیرے لیے تھے، اس سے بے خبر کہ یہ خوبصورت زنجیریں ہیں جو مردوں کو تاعمر قید کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں، ’’ہم فٹ بال کے شائقین اس کی اجازت نہیں دیتے۔ ہماری لغت میں شکست کی اصطلاح موجود نہیں۔ اسے تم ہماری کمزوری سمجھو یا طاقت، یہ ایک بڑی تحریک ہے ہمارے اندر جینے کی۔۔ جس دن ہم ہار تسلیم کر لیں، ہم انسان نہ رہیں، ایک بغیر ہوا کی گیند میں بدل جائیں۔‘‘
ٹیوب ویل! اوہ معاف کیجئے، ہم ٹیوب ویل کے پاس واپس چلتے ہیں۔۔ مجھے دوسری بار کہنے دیں، یہ ایک بہت ہی پرانا ٹیوب ویل ہے۔۔ اور اب تو اس گلی سے باہر جاتے یا واپس اندر آتے لوگوں کو ایک طرح سے اسے ناکارہ دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے۔
’’تمھیں خبر بھی ہے،‘‘ ایک بار گلی کے ایک مکین کو میں نے اپنے ساتھی کو بتاتے سنا تھا، جو باہر کا آدمی تھا، ’’اس ٹیوب ویل کے بارے میں بہت ساری افواہیں مشہور ہیں۔‘‘
’’اچھا؟ اور میں سمجھتا تھا یہ بس یوں ہی سا ایک ہینڈ پمپ ہے، جیسے بہت ساری جگہوں پر نظر آتے ہیں جو اپنا دن دیکھ چکے۔۔‘‘ باہر کا آدمی کہتا ہے، ’’میں جب بھی تمہارے گھر آتا ہوں، اس سے ٹکرا جاتا ہوں۔ تم لوگ اسے کیسے برداشت کرتے ہو؟ ویسے وہ افواہیں کیا ہیں؟ وہ افواہیں یقیناً کافی طاقتور ہوں گی جو یہ ہینڈ پمپ گلی کے بیچوں بیچ اس طرح کھڑا ہے۔‘‘
’’افواہ یہ ہے کہ اس ٹیوب ویل سے کبھی پانی نہیں نکلا۔‘‘
’’یہ کوئی نئی بات ہے؟‘‘ اسے جواب ملا، ’’اس سے اس کی اہمیت بھلا کیسے بڑھ سکتی ہے؟ اس ملک میں سینکڑوں چیزیں ہیں، جنہوں نے شروع سے ہی اپنا کام کرنا بند کر دیا ہے۔ شاید اور بھی کوئی وجہ ہو، جسے تم نہیں جانتے۔‘‘
’’میں کیسے نہیں جان سکتا؟ مجھے یہاں رہتے بیس برس سے زیادہ ہو گئے ہیں۔‘‘
وہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ یہ ٹیوب ویل پندرہ برس پہلے مقامی لوگوں کی مانگ پر الیکشن کے اعلان سے قبل لگوایا گیا تھا۔۔ مگر ایک لمبی تقریر کے بعد جب لیڈر نے اس ٹیوب ویل کا افتتاح کیا تو اس سے ایک قطرہ پانی نہ نکلا جبکہ ٹیسٹ کے دوران یہ لگاتار پانی اگلتا رہا تھا۔ اسے فوراً نیتا نے سبوتاژ قرار دیا اور مخالف پارٹی کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ اس کے دوسرے دن ایک کتا اس ٹیوب ویل کے سامنے مرا ہوا پایا گیا۔ چونکہ اس کا ایک سیاسی پہلو نکل آیا تھا، کسی نے بھی اس کتے کو وہاں سے ہٹانے کی جرأت نہیں کی اور وہ کئی دنوں تک نل کے سامنے پڑا مہکتا رہا۔ لیڈر کو تو اسمبلی الیکشن میں ہر حال میں جیتنا تھا مگر یہ ٹیوب ویل ان دنوں کی یادگار کے طور پر رہ گیا۔ اس سے کم از کم ہم پر یہ راز تو کھلا کہ ہمارے کچھ نیتا کچھ کرنے کی ضرور کوشش کرتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آخر میں ٹیوب ویل پیاسا کا پیاسا رہ جاتا ہے۔
ہمارے محلے کا کاؤنسلر گنموئے گنگا رام ہمیشہ ہمارے گھر آیا کرتا ہے کیونکہ ہر الیکشن کے موقعے پر بندنا اپنی مانگ میں سیندور سجائے، کندھے پر اوڑھنی یا شال رکھے پارٹی کے لیے پرچار کرنے نکل پڑتی تھی۔
’’ہمیں اس ٹیوب ویل کو کام کے لائق بنانا چاہیے۔۔‘‘ ایک دن میں اس سے کہتا ہوں۔
’’کیا فائدہ؟‘‘گنگا رام کہتا ہے، ’’اس سے خوامخواہ گلی میں آنے جانے والوں کو تکلیف ہوگی۔ پانی کی نکاسی کا انتظام تو اب اس جگہ ہونے سے رہا، خوامخواہ یہ گلی گندی دکھائی دے گی۔ ویسے اب اس کی ضرورت بھی بھلا کسے ہے؟ زیادہ تر گھروں میں نل کا انتظام ہو چکا ہے۔ اوپر سے گرمی کے دنوں میں کارپوریشن کا ٹینکر یہاں روز پانی لے کر آیا کرتا ہے۔‘‘
’’تو اس ٹیوب ویل کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔‘‘
’’یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ سنکھو دا نے خود اسے لگوایا تھا۔‘‘ وہ ایم ایل اے کا ذکر کرتا ہے جو ان دنوں سرکار میں منسٹر کے عہدے پر فائز ہے، ’’لگھودا، آپ بھی کانگریسیوں جیسی باتیں نہ کیا کرو۔ بندنا، تم لگھو دا کو سمجھاتی کیوں نہیں؟‘‘
’’میرا اتنا دماغ نہیں کہ تمہارے لگھو دا کو سمجھاؤں،‘‘ بندنا نے جواب دیا، ’’وہ ہر آئے دن کوئی نہ کوئی نئی بات دماغ میں بھرتے رہتے ہیں۔‘‘
’’میں تو اس سے پانی نکال کر ہی دم لوں گا،‘‘ میں نے الٹی میٹم دیتے ہوے کہا، ’’اور گنگا رام، تم لوگ اسے سیاست کا معاملہ نہ بناؤ۔‘‘
’’ارے نہیں لگھو دا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ ہم کیا آپ کو نہیں جانتے؟ یہاں کون آپ کی عزت نہیں کرتا؟‘‘
مجھے پتا ہے وہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ یہ سالے سیاست دان، یہ اپنے منھ کے اندر جانے کتنی زبانیں رکھتے ہیں۔
اس دن گلی میں، میں دیر تک چہل قدمی کرتا رہتا ہوں۔ چھوٹے چھوٹے کھمبوں پر بلب جل اٹھے ہیں۔ ٹیوب ویل کا سایہ کسی تیر انداز کی طرح نکڑ سے اندر کی طرف پھیل گیا ہے۔ اسی گلی میں کھیل کر میں جوان ہوا تھا۔ ایک دن اس گلی سے میری ارتھی اٹھنے والی تھی اور لوگ مجھے ٹرک میں لاد کر موڑھی پھینکتے ہوے نیم تلہ کا راستہ لینے والے تھے۔ کیا میں یوں ہی مر جاؤں گا؟ ایسا کچھ کر کے گزر جانا کیا برا ہوگا، جس سے اس گلی کے لوگ کم از کم مجھے جوڑ کر دیکھتے رہیں، تھوڑے عرصے کے لیے ہی سہی، بلا وجہ ہی سہی۔۔
میں جس آرکیٹیکچر فرم میں نقشہ نویس تھا، وہاں ایک سائٹ انجینئر سے میں نے فون پر رابطہ قائم کیا۔
’’یہ سرکاری نل ہے اور پھر اندر پائپ کی خرابی نکلی تو اس میں سامان کے خرچ کے ساتھ ساتھ مزید کھدائی کا خرچ بھی آ سکتا ہے۔‘‘
’’اس کا میں انتظام کر لوں گا‘‘ میں نے کہا، ’’اس میں سیاست کا اب کوئی معاملہ نہیں رہا اور گلی میں بہت سے لوگ اس معاملے میں میرے ساتھ ہوں گے۔‘‘
’’تو تم اس کے بارے میں کیا کرنا چاہتے ہو؟‘‘
’’یا تو اسے کام کے لائق بناؤ، یا اسے اکھاڑ پھینکو۔‘‘
’’تمھیں یقین ہے کہ یہ اتنا آسان ہے؟‘‘
’’لگتا ہے تم یہ کام نہیں کرنا چاہتے۔۔ مجھے دوسرا آدمی ڈھونڈنا ہوگا۔‘‘
’’ارے نہیں، تم تو بلا وجہ بھڑک اٹھتے ہو۔‘‘ سائٹ انجینئر کی آواز میں نرمی آ گئی، ’’کیا مجھے نہیں پتا کہ تم کس طرح کے انسان ہو؟ اس فرم میں تمہاری کون عزت نہیں کرتا؟‘‘
’’مجھے چکنی چپڑی باتوں میں نہ گھیرو۔ مجھے صاف صاف بتاؤ مجھے کیا کرنا ہوگا، کتنے پیسے کا انتظام کرنا ہوگا۔ آخر کنزیومر کورٹ کس دن کام آئے گی۔‘‘
’’خرچ کے بارے میں تو میرے آدمی کے دیکھنے کے بعد ہی پتا چلے گا۔ ویسے اگر زمین کے اندر کا پائپ صحیح سلامت رہا تو خرچہ بس براے نام آئے گا۔‘‘
’’ویسا ہی ہو۔‘‘ میں فون رکھ دیتا ہوں۔
میں جس میز کے سامنے کھڑے ہوکر نقشے بنایا کرتا تھا، اس کے سامنے ایک کافی بڑی قد آدم کھڑکی تھی، جس کے پٹ باہر کی طرف کھلے ہوے تھے۔ اس سے پرانے کلکتہ کی خستہ حال عمارتیں کسی بد رنگ پینٹنگ کی طرح نظر آتی تھیں۔ ان قدیم عمارتوں کی بھیڑ میں ایک مسجد کے دو یکساں جسامت کے گنبد ابھرے ہوے تھے، جن پر کبوتروں نے اپنا ڈیرا بنا رکھا تھا۔ میں نے ان دونوں گنبدوں کے بیچ جاڑے کے موسم میں ہمیشہ سورج کی لال ٹکیا کو پگھلتے دیکھا ہے۔ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ دنیا اتنی آسان جگہ نہیں ہے، میں خود سے کہتا ہوں۔۔ مگر یہ میری بنائی ہوئی دنیا نہیں ہے اور پھر ہمیں یہ ثابت تو کرنا ہی پڑتا ہے کہ ہم کسی قابل ہیں، کہ ہم اس سیارے پر تھوڑا بہت تو دکھائی دیتے ہیں۔
نمائی گھوشال کے پاس کوئی گردن نہیں ہے۔ اس کے سامنے تپائی پر چائے رکھتے وقت میری بیوی اسے نا پسندیدہ نظروں سے دیکھتی ہے، مگر اس پوری گلی میں وہ میرا سب سے پسندیدہ آدمی ہے۔ کنزیومر کورٹ کا خیال اسی نے میرے دماغ میں ڈالا ہے۔ نمائی گھوشال کے ساتھ میں بچپن سے جوانی تک موہن بگان اسٹیڈیم میں فٹ بال کھیل چکا ہوں اور جب اسے اپنے باپ کی لانڈری سنبھالنی پڑی تو اس نے چار سال کے اندر اندر اس کا دیوالیہ نکال دیا۔
’’مجھے یہ سب بکھیڑا اچھا نہیں لگتا،‘‘ اس نے میرے سامنے اعلان کیا تھا، ’’کیا آدمی اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ ساری زندگی دوسروں کی غلاظت دھوتا رہے؟‘‘
’’ہم اپنی روٹی کے لیے محنت کرتے ہیں۔‘‘ میں نے ایک کمزور سا احتجاج پیش کیا کیونکہ یہ وقت کی مانگ تھی۔ مگر مجھے پتا تھا گھوشال اپنی منطق کے سیلاب میں اسے بہا لے جائےگا۔
’’یہ ہم اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں،‘‘ گھوشال نے جواب دیا، ’’اصل بات یہ ہے کہ ہم سب بوجھ ڈھونے والے جانور ہیں۔ جس کی پیٹھ پر جتنا بوجھ ہو، وہ اپنے آپ کو اتنا ہی خوش قسمت سمجھتا ہے۔‘‘
لانڈری کے بند ہونے کے بعد نمائی نے کچھ دنوں تک ایک پتریکا نکالنے کی کوشش کی تھی اور کندھے سے ایک جھولا لٹکائے گھومتا پھرتا تھا۔ اپنے قلم کار کی شخصیت کو مکمل روپ دینے کے لیے اس نے اپنی ٹھوڑی پرانتہائی سرکش داڑھی اگالی تھی۔ وہ پتریکا تو نہیں چلی، ہاں صحافی کے طور پر نمائی گھوشال چل نکلا اور اس کے تعلقات تجارت اور سیاست کے گلیاروں میں دور دور تک پھیل گئے۔
’’یہ گنموئے گنگا رام تو اوّل نمبر کا گدھا ہے‘‘ اس نے ایک بسکٹ اٹھا کر اپنے قلم کی طرح نوکیلے دانتوں سے اسے چور کرتے ہوے کہا، ’’پہلے میں سیدھے سنکھو دا سے بات کروں گا۔ پھر آگے۔۔ ہر معاملے کی ایک صحیح شروعات ہونی چاہیے، ایک صحیح دشا ہونی چاہیے۔ ارے ہمیں تو اس کے بارے میں بہت پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ ہم بنگالی اسی لیے تو مار کھا جاتے ہیں۔ کبھی بنگال جو آج سوچتا تھا، کل سارا بھارت اسے سوچا کرتا تھا۔ آج یہ حالت ہے کہ سارا بھارت جو آج سوچتا ہے، ہماری کھوپڑی میں وہ بات تین سال بعد آتی ہے۔‘‘
’’سب کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں۔۔ یہ پرانا نل ایک پرانے کرایہ دار کی طرح ہے۔ اسے اکھاڑ پھینکنا آسان نہیں اور کام کے لائق بنانا تو اور بھی مشکل ہے۔ بہت سارے معاملات اس سے جڑے ہوے ہیں، جن کا ہمیں پتا نہیں مگر جو دھیرے دھیرے سامنے آ جائیں گے۔‘‘
’’وہ سب سامنے آئیں تو!‘‘ گھوشال نے اپنے بغیر گردن والے سر کو ایک فاختہ کی طرح پہلے گھڑی کے رخ اور پھر اس کے مخالف موڑتے ہوے کہا، ’’تم نے کچھ سوچنے کی کوشش تو کی، ورنہ آج کل کس کے پاس سوچنے کے لیے وقت ہے۔ سچ پوچھو تو ہم سب مشین بن چکے ہیں۔۔ مشین، جسے دوسرے چلا رہے ہیں۔‘‘
’’یہ نمائی دا خود اپنے کسی کام کا آدمی نہیں، تم اس سے کیا امید رکھتے ہو؟‘‘اس کے جانے کے بعد میری بیوی نے کہا، ’’یہ عجیب سَنَک پال لی ہے تم نے۔۔‘‘
’’ذرا انتظار کرو بندنا‘‘ میں نے نمائی گھوشال کے چھوڑے ہوے بسکٹ کو طشتری سے اٹھا کر چباتے ہوے کہا، ’’اور میرے لیے ایک کپ گرم چائے بنا لاؤ۔ میں ذراچھت کی دھوپ میں بیٹھتا ہوں۔ یہ معاملہ سنگین ہے۔۔ مجھے اس میں تمھاری مدد چاہیے۔‘‘
’’کیسی مدد؟‘‘ بندنا نے چونکتے ہوے کہا، ’’ مجھے اپنے معاملات میں نہ لپیٹو۔ میں کیا تمھیں نہیں جانتی۔ یہ سارا پاگل پن تم اپنے تک ہی محدود رکھو۔‘‘
’’اب شاید اس دنیا کو پاگلوں کی ہی ضرورت ہے۔۔‘‘ میں مسکرا کر کہتا ہوں۔
دو ہفتے گزر گئے ہیں۔ عجیب بات یہ ہے کہ ان دو ہفتوں میں ایک طرح سے میں اس معاملے سے ذرا سا اکتا گیا ہوں۔ اس کی جو بھی وجہ رہی ہو، میری اپنی مصروفیات کا اس میں کوئی دخل نہیں کیونکہ یہ اپنے معمول پر ہیں۔ ان میں نہ کوئی خاص اضافہ ہوا ہے، نہ ہی کوئی کمی آئی ہے۔ دوسرے دنوں کی طرح آج بھی میں میز کے سامنے کھڑا پنسل سے لکیریں کھینچتے کھینچتے اکتا گیا ہوں اور کھڑکی سے باہر تاک رہا ہوں، جہاں عمارتوں کے ہجوم میں مسجد کے گنبدوں پر کبوتر پھڑ پھڑا رہے ہیں۔ ابھی سورج کی ٹکیا کا وقت نہیں آیا ہے۔ ابھی ہماری طرف کی کھڑکی عمارت کے سائے میں ڈوبی ہوئی ہے۔ نیچے سڑک سے گزرتی گاڑیوں کے ہارن لگاتار بج رہے ہیں۔ میں شہر کی اس سمفنی کا ’لطف‘ اٹھا رہا ہوں، جب کریم چائے کی پیالی لیے ہوے اندر داخل ہوتا ہے۔ پیالی تھام کر میں اپنی گدّے دار کرسی کے اندر دھنس جاتا ہوں اور دونوں ٹانگیں میز پر پھیلاکر ہانک لگاتا ہوں۔
’’کریم!‘‘
’’ہاں حضور‘‘ کریم اس عمارت کا لفٹ مین ہے، جو لفٹ کے دائمی طور پر ناکارہ ہوجانے کے بعد ہمارے آفس میں کام کرنے لگا ہے۔ اس کے کان کے لوؤں کے بال کبوتروں کی طرح اجلے اور سفید ہیں۔ وہ ہمارے آفس کے اندر ہی سوتا ہے، آفس کے اندر ہی نماز پڑھتا ہے اور آفس کے پرانے فرنیچر جو برسوں کے استعمال کے سبب چکنے اور سیاہ ہو رہے ہیں ان ہی کا ایک حصہ نظر آتا ہے۔
’’کریم، مرنے کے بعد کہاں دفن ہونے کا ارادہ ہے؟‘‘
’’جہاں بھائی لوگ دفن کر دیں حضور۔۔ گوبرا، باگماری یا سولہ آنا قبرستان۔ سسرے اور کہاں لے جائیں گے۔‘‘
’’تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں؟‘‘
’’اب تو آپ ہی لوگ سب کچھ ہیں حضور۔‘‘
’’تم اپنے گاؤں کیوں نہیں لوٹ جاتے؟ گاؤں کی مٹی، وہاں کی ہوا، وہاں کے لوگ، وہ تمہیں یاد نہیں آتے؟‘‘
’’پچاس برس بعد اب وہاں کون ہمیں پہچانےگا حضور! ‘‘ کریم نے بنچ پر بیٹھتے ہوے کہا، ’’خود اپنا گاؤں اب گاؤں کہاں رہا۔ اب گاؤں کے لوگ شہریوں سے زیادہ سیانے ہو گئے ہیں۔ سالے زمین جائداد کے لیے زیادہ مار کاٹ کرنے لگے ہیں۔ اب تو ان لوگوں سے ہاتھ ملا نے کے بعد اپنی انگلیوں کو گن لینا پڑتا ہے۔‘‘
دیہات کے لوگ سیانے ہو گئے ہیں، گاؤں قصبوں میں بدل گئے ہیں، قصبے شہروں میں، شہر میگا سٹی میں، میٹرو پولس کوسموپولس میں ڈھل گئے ہیں۔ اب ہمارے یہ مہانَگر کسی ملک سے کم نہیں، سب لوگ ایک ملک کے اندر ایک دوسرے ملک میں آباد ہیں، ان کی نہ نظر آنے والی اپنی سرحدیں ہیں، اپنی خاردار باڑھیں ہیں، No man’s land ہیں، ان پر مخصوص پارٹیوں کی سیاسی پکڑ ہے، غنڈوں کی دہشت کا خاص انتظام ہے۔۔۔ ایک ملک کو اور کیا چاہیے؟ میں اپنی عمارت کے نیچے سڑک سے گزرتے وقت ٹرام کی پٹری پر رک گیا ہوں۔ سڑک پر دھواں پھیل رہا ہے۔ بہاری ٹھیلے والے ٹھیلوں پر سامان لادے گزر رہے ہیں۔ بنگالی کلرک اپنی ٹائپ مشینوں پر اونگھ رہے ہیں۔ یہ انگریزوں کے زمانے سے وہاں بیٹھے اونگھتے آ رہے ہیں۔ یہ بہت زیادہ بھات خوری کا نتیجہ ہے۔ ہائی کورٹ کے وکیل اور پیادے اپنی وردیوں میں گھوم رہے ہیں۔ ایک کتا اپنی پچھلی ٹانگ اٹھائے ایک ہائیڈرنٹ پر پیشاب کر رہا ہے۔ اس کے پیشاب کا رنگ بھی کچھ ہوگلی ندی کے پانی کی طرح گدلا ہے، جو اس ہائیڈرنٹ سے باہر آتا ہے۔ کوئی اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ سب لوگوں کو جلدی ہے۔ مجھے بھی جلدی ہے۔ ایک کافی رنگین اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرام گھنٹی بجاتے ہوے ہلال کی شکل میں لال دیگھی کے کنارے سے گزر رہا ہے، پٹریاں بدلتے وقت اس کے پہئے بری طرح کھڑکھڑا رہے ہیں، اندر بیٹھے ہوے لوگوں کے سر ہل رہے ہیں۔
نمائی گھوشال میرے گھر پر میرا انتظار کر رہا ہے۔
’’میں نے سنگھو دا سے بات کی ہے۔ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔‘‘
’’میرے پاس وقت نہیں ہے اور پھر یہ مسئلہ میرے اکیلے کا نہیں ہے۔‘‘
’’تو تم پیچھے ہٹ رہے ہو۔ تمہارا جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔ پہلے تو تم ایسے نہیں تھے۔‘‘
’’اب بھی نہیں ہوں،‘‘ میں کہتا ہوں، ’’مگر میں اس کے پاس کیوں جاؤں؟ یوں بھی یہ نیتا لوگ مجھے نہیں بھاتے۔‘‘
’’تم ایک ناممکن آدمی ہو۔‘‘ نمائی گھوشال مسکرا رہا ہے۔ ’’ویسے سنگھو دا سے تمھیں ملاقات کرنی ہی پڑے گی۔ گھبراؤ مت، وہ اتنا برا آدمی نہیں۔ منسٹر ہے، مگر اب بھی اپنے پرانے مکان میں اپنی معمولی زندگی گزار رہا ہے۔‘‘
’’ہم سب اپنی معمولی زندگیاں گزار رہے ہیں۔ اس سے ہم کوئی تیر نہیں مار لیتے۔۔‘‘ میں کہتا ہوں۔ اس کے چلے جانے کے بعد بندنا مجھ پر برس پڑتی ہے۔
’’عجیب طریقہ ہے یہ تمہارا۔۔ وہ بیچارا تمھارے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے اور تم ہو کہ۔۔۔ آخر تم میں تبدیلی کب آئے گی؟‘‘
’’اب اس عمر میں میرے اندر کیا تبدیلی آئے گی۔ ایک بوڑھے مرغے سے تم کسی نئے پینترے کی امید مت کرو۔‘‘ میں اپنے کمرے کی اونچی پلنگ پر چڑھتے ہوے کہتا ہوں جس کے نیچے ہمارے گھر کا الم غلم سامان بھرا پڑا ہے۔ ہم نچلے متوسط طبقے کے لوگ، چاہے ہمارے سامانوں کا کوئی بھی مصرف نہ رہ گیا ہو، انہیں پھینکنے میں یقین نہیں رکھتے، ’’اور نمائی گھوشال کے بارے میں فکر نہ کرو۔ ہم لوگ ایک دوسرے کو زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں۔ ہماری دوستی اس وقت کی ہے، جب ہم ننگے گھوما کرتے تھے۔۔ تم تو بہت بعد کی چیز ہو۔‘‘
اور گرچہ بندنا کو میری بات سے چوٹ پہنچتی ہے، میں اس کا نوٹس نہیں لیتا۔ اس رات مجھے بہت دیر سے نیند آتی ہے۔ خواب میں بار بار میں اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹرام کو اپنی پٹری سے گزرتے دیکھتا ہوں۔ ہر بار مجھے اس کے اندر کریم بیٹھا نظر آتا ہے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر مجھے ٹرام کے اندرآنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ آخرکار میں ٹرام کے پائیدان پر لٹک جاتا ہوں۔ مگر ٹرام کا کنڈکٹر مجھے ٹرام سے نیچے اترنے کی ہدایت دے رہا ہے جو دیر سے میری تگ و دو پر نظر رکھے ہوے تھا۔
’’آپ کو سمجھنا چاہیے۔ ٹرام ڈپو کے اندر جا رہا ہے۔‘‘
صبح میں جاگ کر سر تکیہ پر ٹکائے اسی واقعے کو سوچ رہا ہوں۔ شہر دھیرے دھیرے دھویں اور دھند کی چادر سے ابھر رہا ہے۔ ایک عجیب باسی مہک ہے جو در و دیوار سے آ رہی ہے۔ کیا میری ناک اچانک زیادہ کام کرنے لگی ہے؟ ہاتھ منھ دھو کر میں کھڑکی کے سامنے زیر جاموں سے لدی بید کی کرسی پر بیٹھا سورج کی کرنوں کو عمارتوں کے درمیان کے خلاؤں میں نیزوں کی طرح داخل ہوتے دیکھ رہا ہوں۔ گلی میں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہے۔ ہمارا کتا ہیرا من جاگ چکا ہے اور ایک عجیب دبی دبی سی آواز نکال رہا ہے جیسے اپنے وجود کا احساس دلا رہا ہو۔ اخبار والا اخبار پھینک کر جا چکا ہے۔ گوالا اپنی سائکل پر کنستر کھڑکاتے ہوے گزر رہا ہے۔ خاکروب گلی میں جھاڑو لگا رہا ہے۔ مشنری اسکول میں جانے والے بچے اسکول کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ لگتا ہے ایک ہی فلم ہے جسے میں روز دیکھنے پر مجبور ہوں۔ بندنا نمودار ہوتی ہے اور چائے کی گرم پیالی اخبار کے ساتھ میری ہتھیلی میں تھما دیتی ہے۔
’’گڈ مارننگ۔۔‘‘ وہ مجھ سے کہتی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندنا مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نظر آتی ہے اور میں سوچا کرتا ہوں وہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید میں پتھر بن کر کسی دیوار سے لگا رہ جاتا۔ مگر آج وہ کچھ زیادہ مسکرا رہی ہے۔ یہ مسکراہٹ بلا وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری بہت سی عادتوں کا کوئی جواز نہیں ہوتا۔
اس دن آفس سے میں جلدی نکلتا ہوں۔ آج میرا ارادہ نمائی گھوشال کے ساتھ سنگھو دا سے ملنے کا ہے۔ گلی سے مڑتے وقت میں ہمیشہ کی طرح ٹیوب ویل سے بچنے کے لیے کنارے کی طرف دبنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں گرتے گرتے بچتا ہوں۔ ٹیوب ویل اپنی جگہ پر نہیں ہے۔
کیا میں کسی دوسری گلی میں آ نکلا ہوں؟ نہیں، یہ گلی تو ہماری ہی ہے، صرف ٹیوب ویل اپنی جگہ سے غائب ہے، جس کے سبب گلی کچھ زیادہ ہی کشادہ اور قدرے اجنبی نظر آ رہی ہے۔ ٹیوب ویل کی جگہ پر کھڑے ہوکر میں دیکھتا ہوں، زمین پر ایک بیضوی سوراخ بن گیا ہے، جسے مٹی سے لبا لب بھر دیا گیا ہے۔
میں اس جگہ دیر تک کھڑا رہتا ہوں کہ مجھے دیوار گیر مندر کا پجاری مہالٹ گوسوامی آتا دکھائی دیتا ہے۔
’’یہ ٹیوب ویل کہاں گیا؟‘‘ میں اس سے پوچھتا ہوں، جیسے وہ اس کے لیے جواب دہ ہو۔
’’تین مستری آئے تھے لگھو دا۔ دن بھر کام کرتے رہے۔ سارا سامان یہاں تک کہ اندر سے زنگ کھائے ہوے پائپ تک نکال کر لے گئے۔۔ آخر آپ نے یہ کر ہی دکھایا۔‘‘
’’میں نے کیا کیاہے۔ خوامخواہ میرا نام مت لو!‘‘ میں تنک کر کہتا ہوں اور اپنے گھر کی طرف بڑھ جاتا ہوں۔ میں دیکھتا ہوں آج میرے ہر قدم پر دروازے اور کھڑکیاں کھل رہی ہیں، لوگوں کے مسکراتے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ سب لوگ اپنائیت کے ساتھ میری طرف تاک رہے ہیں۔ ایک مکان کے سامنے ایک ہاتھ رکشا بھی زمین پر ٹکا ہوا ہے، جسے چلانے والا اس کے پائیدان پر بیٹھا اطمینان سے بیڑی پی رہا ہے۔ کل تک کوئی رکشا اندر نہیں آ پاتا تھا۔ اب تو یہ گلی ایسی ہو گئی ہے کہ ڈرائیور اگر راضی ہو تو ٹیکسی بھی اندر تک آ سکتی ہے۔
’’سارا محلہ تم سے بہت خوش ہے۔‘‘ ہاتھ منھ دھو کر باتھ روم سے باہر آنے پر بندنا میرے ہاتھ میں تولیہ دے کر مسکراتی ہے۔ ’’واقعی یہ نل یہاں سے ہٹ نہ گیا ہوتا تو ہمیں کبھی اندازہ نہ ہوتا کہ ہماری گلی کتنی کشادہ ہے۔‘‘
’’آخر گدھا گنگا رام نے یہ کر ہی ڈالا۔۔‘‘ میں کہتا ہوں۔
’’گنگا رام؟‘‘ بندنا کی آنکھوں میں حیرت ہے، ’’وہ تو خود آپ کو بدھائی دینے کے لیے آیا تھا۔‘‘
’’مجھے کیوں؟ میں نے کیا کیا؟‘‘ میں سوچ میں پڑ گیا۔ یہ گنگا رام نہیں تو یقیناً نمائی گھوشال کا کارنامہ ہے۔۔ مگر جلد مجھ پر یہ راز کھل گیا کہ نہ یہ نمائی گھوشال کا کام تھا نہ سائٹ انجینئر بپا رائے کا، جس سے میں نے اس سلسلے میں بات کی تھی۔ میں اس گتھی کو سلجھا نہیں پا رہا تھا اور اگرچہ اس دن کے بعد ہمیشہ میں ایمانداری کے ساتھ اس بات سے انکار کرتا رہا مگر سارے محلے کا خیال میرے اس انکار کے سبب اور بھی یقین میں بدل گیا۔ نہ صرف لوگ میری طرف احترام سے تاکنے لگے تھے بلکہ سنکی پریمل دا بھی میری پیٹھ ٹھونکنے سے باز نہ آئے۔
’’میں بھوانی شیو ٹھاکر کی بہت ساری باتیں تم میں دیکھ رہا ہوں۔‘‘
شاید ٹیوب ویل نے لوگوں کو کچھ زیادہ ہی ستایا تھا!
دو ہفتے گزر گئے ہیں۔ میں نے احتجاج کرنا بند کر دیا ہے۔ اب تو اس جگہ سے گزرتے ہوے خود مجھے یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ یہ میرا ہی کارنامہ ہے۔
’’یہ پی ڈبلیو ڈی والے ہوں گے۔ اس میں حیرانی کی کیا بات ہے،‘‘ سائٹ انجینئر نے مجھ سے کہا تھا، ’’یہ اتفاق ہے کہ تمہیں اس کا خیال آیا اور انہوں نے ٹھیک وقت پر ایسا سوچا۔ یا پھر کون جانے لوہے کا کوئی کباڑی اس موقعے کا فائدہ اٹھا کر سارا سامان لے کر چلتا بنا ہو۔ کلکتہ جیسے پرانے شہر میں تو یہ روز کا قصہ ہے۔اب اس میں شرمندگی کی کیا بات ہے۔ اچھا ہوا نا، سر درد بھی جاتا رہا اور سر بھی بچ گیا۔‘‘
یہ اس انجینئر کے مذاق کرنے کا بھونڈا طریقہ تھا۔ بپا رائے! مجھے یہ آدمی پسند نہیں۔ میں اسے پہلے کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح جان گیا ہوں۔ وہ صرف کام ٹالنے میں ماہر ہے۔ اگر اس نے ایمانداری سے کام لیا ہوتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ ہمیں زندگی میں زیادہ تر لوگ اچھے اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ انھیں آزمانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس تھوڑا سا تیزاب ان پر ڈالو اور اوپر کی دھات زائل ہونے لگتی ہے، اندر کا بھوت باہر نکل آتا ہے۔
اب اس بات کو چھ مہینے گزر چکے ہیں۔ میرے آفس میں مصروفیات پہلے سے کچھ زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ شہر کے مضافات میں بڑے بڑے رہائشی علاقے بننے لگے ہیں۔اچانک اس میگا سٹی میں لوگوں کو گھر بنانے کا جنون سا ہو گیا ہے۔ کاغذ پر پنسل کی مدد سے لکیریں کھینچتے ہوے اب مجھے مسجد کے گنبدوں کے اوپر پر پھڑ پھڑاتے کبوتروں کے لیے کم موقع ملتا ہے۔ کبھی کبھی تو ان کے بیچ سورج کی ٹکیا پوری طرح پگھل چکی ہوتی ہے اور مجھے اس کا پتا بھی نہیں چلتا۔ پھر ایک دن میرے پاس کام نہیں رہتا اور میں چائے پیتے ہوے اپنی دونوں ٹانگیں میز پر پھیلا کر ہانک لگاتا ہوں۔
’’کریم!‘‘
’’ہاں حضور۔‘‘ کریم کے دبلے پتلے جسم کا سیلہوئٹ پرانے فرنیچروں کی دھند سے ابھرتا ہے۔
’’کریم، تم تو لفٹ مین کے طور پر اس عمارت میں کام کرتے تھے نا؟‘‘
’’ہاں حضور۔‘‘
’’تب تو تمہیں تنخواہ بھی ملتی ہوگی؟‘‘
’’کیسی تنخواہ حضور۔۔ لفٹ ہی کون سا کام کرتا ہے؟‘‘
’’کیا کہا، لفٹ کام نہیں کرتا؟ تو اس میں تمہارا کیا قصور؟ انہیں اس کی مرمت کروانی چاہیے۔‘‘
’’یہ انگریزوں کے زمانے کا لفٹ ہے۔ اب اس کے کل پرزے نہیں ملتے۔ وہ بیچارے بھی کیا کریں گے۔‘‘
’’سب ملتے ہیں۔ تم ان لوگوں کو نہیں جانتے۔ ہم ہندوستانی ایک بہت ہی چالاک قوم ہیں۔ میں نے اس سے بھی پرانے لفٹ کو کلکتہ کی عمارتوں میں کام کرتے دیکھا ہے۔ تم کل دس بجے مجھ سے ملنا۔ ہم ٹرسٹ کے سیکرٹری سے ملنے جائیں گے۔ اگر انہوں نے کچھ نہ کیا تو میرا ایک دوست ہے نمائی گھوشال۔ اسے کنزیومر کورٹ کے بارے میں پورا تجربہ ہے۔ ہمیں اس معاملے کو ویسے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ یہ تمہاری تنخواہ کا ہی نہیں بلکہ ہم لوگوں کے دل کا سوال ہے۔ کتنی پرانی عمارت ہے یہ، کتنی اونچی اونچی سیڑھیاں ہیں اس کی اور ہمیں کتنی ساری سیڑھیاں ہر روز طے کرنی پڑتی ہیں۔کوئی حادثہ ہو گیا تو؟ کیا لوگ کرایہ نہیں دیتے؟‘‘
(جبکہ مجھے پتا تھا لوگ جو کرایہ دیتے ہیں، اس سے اس عمارت کا میونسپلٹی کا ٹیکس بھرنا بھی ممکن نہ تھا۔)
’’حضور آپ کو لگتا ہے یہ لفٹ پھر سے چلنے لگے گا؟‘‘ کریم کی آنکھوں میں ایک روشنی جاگ اٹھی ہے۔ وہ ایک نیا انسان نظر آ رہا ہے، جیسے پھر سے اسے زندگی میں ایک مقصد ہاتھ آ گیا ہو۔
’’بالکل!‘‘ میں اس کی طرف مسکراتے ہوے دیکھتا ہوں۔ ’’اس ملک میں کیا نہیں ہو سکتا؟ صرف ہمارے اندر ارادے کی کمی ہے۔ میں تمہیں ایک ٹیوب ویل کی کہانی سناتا ہوں جو بلا وجہ لوگوں کا راستہ روکا کرتا تھا۔‘‘