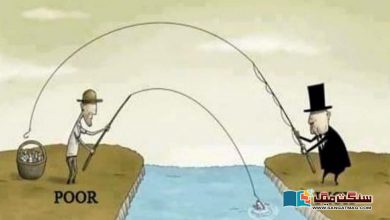فاطمہ کا تعلق ایک متوسط خاندان سے ہے۔ وہ ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں ملازمت کرتی ہیں اور ان دنوں اپنی والدہ کے علاج کے لیے ملازمت کے ساتھ ساتھ فری لانسنگ بھی کرتی ہیں تاکہ اپنی والدہ کے مہنگے علاج کے اخراجات اُٹھا سکیں۔ ان کی والدہ گزشتہ دو برسوں سے بریسٹ کینسر کا شکار ہیں اور اب صحتیاب ہو رہی ہیں
چھبیس سالہ فاطمہ کا کہنا ہے، ”میری ماں بہت خوبصورت تھیں اور میں انہیں کمزور ہوتا دیکھ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر جھائیاں، نشانات، تکلیف دہ علاج کا کرب صاف نظر آ رہا ہوتا تھا۔ میں اکثر یہ سوچ کر رونے لگتی تھی کہ اگر امی نہ رہیں تو میرا کیا ہوگا؟ یہ سوال مجھے اکثر سونے نہیں دیتا تھا“
کینسر کے علاج کے دوران جہاں انہیں اپنی والدہ کی گرتی صحت اور علاج میں درکار کثیر رقم نے پریشان کر رکھا ہے، وہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ان مراحل سے کہیں زیادہ مشکل ان سماجی رویوں کو جھیلنا ہے، جو ایک مریض کے ساتھ ساتھ اس کے اہلِ خانہ کی ہمت کو توڑ دیتے ہیں
کینسر کا نام سنتے ہی ذہن میں پہلا خیال یہی آتا ہے کہ مریض کے پاس اب کتنا وقت ہے؟ یہ سوال جہاں مریض کے اہلِ خانہ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، وہیں متعلقین بھی اس طرح کے بہت سے سوالات متاثرہ خاندان سے کرتے دکھائی دیتے ہیں
یہ ایک عمومی رویہ ہے مثلاً اگر کسی خاتون کو کینسر ہوا ہے تو اب اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ علاج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ گھر اور بچوں کو کون سنبھالے گا؟ اور اگر مریض مرد ہے تو سوال مختلف ہوں گے کہ علاج کے دوران ملازمت کیسے ہوگی؟ بیوی بچوں کا کیا ہوگا؟ علاج کا خرچہ کون اٹھائے گا؟
یوں تو یہ سوالات یقینی طور پر مریض اور اس کے اہلِ خانہ کے ذہنوں میں بھی ہوتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے اُس وقت سب سے اہم اپنے پیارے کا علاج اور اس کی صحت ہوتا ہے، مگر معاشرہ انہیں ہر وقت یہ پوچھ پوچھ کر جتانے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ ان کے لیے بہت فکرمند ہیں، جس کا اثر منفی ہی ہوتا ہے
چھوٹے بچوں کی ماں نبیلہ حنیف کو 2008 میں چوالیس سال کی عمر میں (رینل سیل کارسینوما میٹیس ٹیٹک) کینسر کی تشخیص ہوئی۔ ویسے تو ان کا علاج تشخیص کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا لیکن 2014 میں یہ کینسر جسم کے دیگر حصوں میں پھیل گیا
مختلف سرجریز، کیمو، ادویات اور دیگر کٹھن مراحل کو برداشت کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتی نبیلہ کہتی ہیں ”لوگوں کا بار بار یہ پوچھنا کہ ’یہ بیماری کیسے ہوئی؟ اب کیا حال ہے؟ کیسے جیو گی؟‘ جیسے سوالات کبھی کبھی آپ کی ہمت کو توڑنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔“
نبیلہ کا کہنا ہے ”موت تو برحق ہے لیکن اس بیماری کا علاج بھی اتنا تکلیف دہ ہے کہ آپ راحت محسوس نہیں کرتے۔ روزانہ طبیعت میں گراوٹ محسوس کرنا، چیزوں، کھانے پینے، یہاں تک کے لوگوں سے بھی بیزاریت ہونے لگتی ہے۔ اس میں اگر آپ کو منفی رویوں کا بھی سامنا کرنا پڑے تو اور بھی مشکل ہو جاتا ہے۔“
وہ کہتی ہیں ”میں نے اپنے بچوں کے لیے ہمت کی اور ڈٹ کر اس بیماری کا مقابلہ کیا، جس میں میرے معالجین کے ساتھ ساتھ وہ لوگ بھی شامل ہیں، جنہوں نے میری ہمت بڑھائے رکھی“
فاطمہ والدہ کے علاج کے دوران اپنے قریبی رشتے داروں کا رویوں کے یکسر تبدیل ہونے کی شکایت کرتی ہیں ”اکثر لوگ یہ کہتے تھے کہ جب مالی حیثیت نہیں تو نجی اسپتال جانے کی ضرورت کیا تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میری امی کی ایک دوست نے بہت رعونت سے یہ بھی کہا کہ ’ہم اتنا صدقہ خیرات نکالتے ہیں تو اس کے علاج کے لیے تھوڑی بہت مدد کر ہی سکتے ہیں۔’ یہ وہ جملے اور رویے تھے جنہوں نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا تھا۔“
ان کا کہنا تھا کہ ہم بہن بھائی ان رویوں اور امی کی صحت کی فکر پر بات تو کرتے تھے، لیکن روتے پھر بھی اکیلے تھے
فاطمہ بتاتی ہیں ”مجھے پیسوں کے اشد ضرورت تھی، ہر تین ہفتے بعد ہونے والی کیمو کے لیے تیس سے چالیس ہزار کی رقم درکار ہوتی تھی، جسے پورا کرنا ایک امتحان لگتا تھا۔ میری اس پریشانی سے دفتر واقف تھا۔ ایک روز میرے باس نے مجھے بلا کر امی کے علاج میں لگنے والی رقم کا ایک بڑا حصہ دیا اور کہا کہ یہ تو ہو گیا اب یہ بتائیں کہ میں اور کیا مدد کر سکتا ہوں؟ مجھے ایک لمحے کو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی پرایا بھی میری اس مشکل وقت میں ایسے مدد کر سکتا ہے، میری بے یقینی کی اہم وجہ یہی تھی کہ میں اپنوں کو آزما چکی تھی۔“
تیس سالہ اریبہ محمود کے والد دو سال مثانے کے کینسر کا شکار رہے۔ والد کی بیماری کے دوران ان کے بھائی بہن ساری بھاگ دوڑ کرتے رہے۔ ان کے بہن بھائی اس وقت پڑھ رہے تھے اور گھر کے واحد کفیل والد تھے، جنہوں نے اپنے بچوں پر کبھی کوئی ذمے داری نہیں ڈالی تھی
ان کے والد کے علاج میں خرچ ہونے والی ساری رقم وہ تھی، جو ان کے والد نے اپنی ساری زندگی کی نوکری میں بیٹیوں کی شادی کے لیے بچا رکھی تھی
اریبہ بتاتی ہیں ”مجھے یاد ہے جب میرے والد کینسر سے لڑ رہے تھے تو میں اسپتال کے کوریڈور میں اکیلی بیٹھی رو رہی ہوتی تھی اور میرے والد کے رشتے دار جب انہیں نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھنے آتے تھے تو ان کے کمرے میں ہنسی مذاق کر رہے ہوتے تھے۔۔ کسی نے بھی ہمارے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی کے دو بول نہیں بولے، بلکہ یہ پوچھا جاتا تھا کہ اب تک کتنی رقم خرچ ہو گئی ہے یا یہ کہتے کہ ہائے ماموں کے بچے تو ابھی پڑھ رہے ہیں، کاش وہ کسی بچے کی خوشی ہی دیکھ لیتے۔“
اریبہ نے کہا ”یہاں تک کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو بھی ہم اپنے گھر تعزیت کے لیے آئے لوگوں کے سامنے کھانے کی پلیٹیں رکھ رہے تھے۔ نہ ہمیں ان کے علاج کے دوران کسی نے تسلی دی، نہ بعد میں کسی نے پوچھا۔“
خسرو ممتاز کی اہلیہ برین ٹیومر کا شکار رہیں۔ اس بیماری کا انہوں نے بہت ہمت سے مقابلہ کیا۔ خسرو کے مطابق، ”جس روز مجھے ڈاکٹر نے یہ بتایا کہ آپ کی اہلیہ کے پاس چھ ماہ کا وقت بچا ہے تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لمحہ میرے لیے زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتا سکتا تھا نہ اپنی اہلیہ کو نہ ان کی والدہ اور اہلِ خانہ کو، اس وقت میرے پاس کوئی ایسا فرد نہیں تھا، جس سے میں اس خبر کو شیئر کر سکتا۔ مجھے تنِ تنہا اس بات کو خود تک محدود رکھنا پڑا۔“
خسرو ممتاز بتاتے ہیں ”وہ الگ بات ہے کہ میری بیوی نے بہت ہمت سے اپنے علاج کو جاری رکھتے ہوئے اس چھ ماہ کو پندرہ ماہ میں تبدیل کر دیا۔ وہ جینا چاہتی تھیں، اسی لیے اپنے علاج کے تمام فیصلے خود کرتی تھیں۔ کب دوا لینی ہے، کب ریڈیو اور کیمو کروانی ہے، انہیں سب یاد رہتا تھا۔“
خسرو کے مطابق ”میں سمجھتا ہوں کہ مریض خود بھی اپنی تکلیف کو اپنے پیاروں کے سامنے اس طرح نہیں بیان کرتے، جس طرح انہیں کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ وہ احساس اور محبت ہے، جو وہ اپنے پیاروں سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جس ذہنی اذیت اور دباؤ سے ہم گزر رہے ہوتے ہیں، ہم بھی اس مریض کے سامنے اپنے وہ جذبات عیاں نہیں کر پاتے، کیوں کہ ہم انہیں ہارتا ہوا یا ناامید نہیں دیکھ سکتے۔“
وہ کہتے ہیں ”مریض کی ہمت بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ ان کے سامنے آپ ہمت بڑھاتے رہیں۔۔ لیکن ایسا ضرور ہے کہ ہمارے اردگرد بسنے والے کچھ لوگ اس بات کا احساس نہیں کر پاتے کہ وہ ہماری نجی زندگی کے بارے میں کچھ ایسا جاننے کے خواہش مند ہیں، جس کا جاننا ان کا حق نہیں۔“
فاطمہ کے مطابق وہ اپنی والدہ کے علاج کے دوران مسلسل ذہنی دباؤ کا شکار رہیں۔ انہیں کئی ایسے وسوسے اور اندیشوں نے گھیرا ہوا تھا، جس کے سبب وہ لوگوں سے کٹ کر رہ گئیں۔
وہ کہتی ہیں ”جب میں نے دیکھ لیا کہ لوگوں کے چبھتے سوالات میری والدہ اور ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تو میرے اور بھائی بہن کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ ہم ایسے لوگوں سے قطع تعلق کرلیں۔ اس کا کسی حد تک فائدہ تو ہوا لیکن میں نے محسوس کیا کہ وہ تمام دوست، رشتے جنہیں میں اپنے برے وقت کا ساتھی سمجھتی تھی، وہ سب بھی دور ہو گئے اور یوں میں اکیلی پڑ گئی۔ اب میرے دل و دماغ میں جو بھی چل رہا ہوتا، نہ میں وہ کہہ سکتی تھی، نہ ہی اس کا اظہار کر سکتی تھی۔ امی کے سامنے تو ہم سب خوش ہی رہتے تھے کہ اگر انہیں اندازہ ہو گیا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، تو وہ کہیں ہمت نہ ہار جائیں۔“
اریبہ کا کہنا ہے ”مجھے وہ لمحہ کبھی نہیں بھول سکتا، جب ہم ابو سے ملنے اسپتال پہنچے اور اس وقت تک ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ میری بڑی بہن نے ہم دونوں بہنوں کو جب یہ اطلاع دی تو ہماری زبان سے پہلا جملہ یہ ادا ہوا کہ اب ہمارا کیا ہوگا؟ ابو ہمیں لوگوں کے رحم و کرم پر کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں۔“
خسرو ممتاز نے اپنی اہلیہ کی وفات کے بعد اس بات کا ارادہ کیا کہ کینسر سے لڑنے والے مریضوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والے اہلِ خانہ کے لیے ایک ایسا سپورٹ گروپ ہونا چاہیے، جہاں لوگ اپنی کہانیاں، خوف، اندیشے اور مشکلات کو اپنے جیسے لوگوں کے ساتھ بانٹ سکیں اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔
خسرو بتاتے ہیں ”میں نے دنیا بھر میں ایسے سپورٹ گروپس دیکھ رکھے تھے لیکن بیگم کی وفات کے آٹھ ماہ بعد میں نے اس پر کراچی کے آغا خان اسپتال کے آنکولوجی ڈپارٹمنٹ کے معالجین سے بات کی، جس پر ان کی جانب سے تعاون کا یقین دلایا گیا۔ یوں ہم نے ’ہمسفر‘ کے نام سے ایک سپورٹ گروپ بنایا، جس میں مختلف سیشنز میں کینسر سے لڑنے والے باہمت مریض، دوسرے مریضوں کا حوصلہ بڑھاتے ہیں۔“
اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کسی حد تک لوگوں کی تکالیف اور دکھوں کو کم کیا جائے۔ جب کوئی مریض جینے کی امید کھونے لگے تو دوسرے مریض کو دیکھ کر یا اس کے اہلِ خانہ کی بات کو سن کر پھر سے جینے کی خواہش کو زندہ کرلے۔ یہاں لوگوں کو حوصلہ ملتا ہے، ہمت اور نئے دوست بھی اور اس سے اچھا تو کچھ ہو نہیں سکتا۔
سن 2008 سے کینسر سے لڑنے والی نبیلہ حنیف باقاعدگی سے اس گروپ کے سیشن میں نہ صرف شرکت کرتی ہیں، بلکہ کینسر سے لڑنے والے کئی مریضوں کی ہمت بھی بڑھاتی ہیں۔ ہمیشہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے نبیلہ مریضوں اور ان کی دیکھ بھال کرنے والوں کو نہ صرف اپنی کہانی سناتی ہیں بلکہ ان کے گرد جمع معالجین کا ہنسی مذاق بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ کتنی زندہ دل خاتون ہیں۔
اریبہ کا کہنا ہے ”زندگی کا ایک دکھ والد کو کھو دینے کا ہے تو دوسرا دکھ یہ ہے کہ جب لوگ ایسی دل دکھانے والی باتیں کر رہے ہوتے تھے تو میرے والد آنکھیں بند کیے وہ سب سن رہے ہوتے تھے۔۔ اگر وہ واقعی نیند میں ہوتے تو ان کی بند آنکھوں سے بہنے والے آنسو ان کی قمیص کا کالر جذب نہ کر رہا ہوتا“
اریبہ کہتی ہیں، ”ایک کیمو تو وہ اسپتال سے کروا کر آتے تھے اور دوسری کیمو لوگوں کے رویے تھے، جس کی تکلیف کا وہ اظہار بھی نہیں کر پاتے تھے۔۔ کاش کہ لوگ سمجھیں کہ اگر کسی کے گھر کوئی بیمار ہے تو وہ خاندان اس وقت کتنا حساس ہوگا۔۔ اگر وہ اسے حوصلہ نہیں دے سکتے تو تکلیف بھی نہ دیں۔“
نوٹ: اس فیچر کی تیاری میں وائس آف امریکہ میں شائع سدرہ ڈار کے ایک مضمون سے مدد لی گئی۔