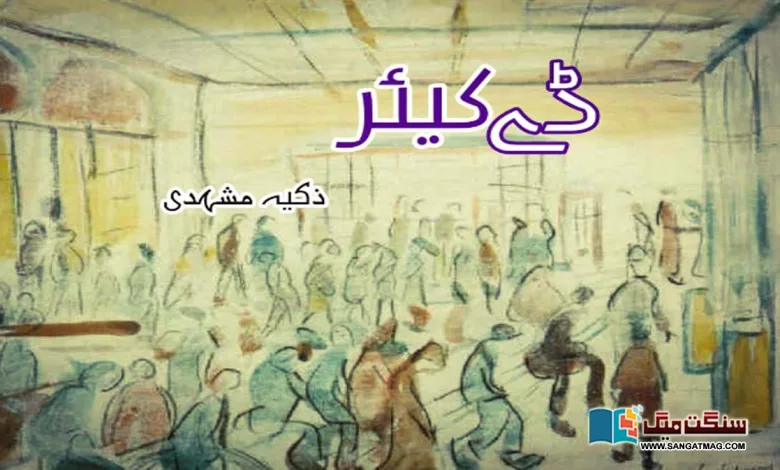
وہاں ہمیشہ میلہ لگا رہتا تھا۔ کھوے سے کھوا چھلتا۔ خلقت یوں امڈی آتی تھی جیسے مفت کچھ بٹ رہا ہو۔۔ لیکن مفت کچھ بٹتا ہوتا تو کیا سب کے چہرے ایسے ہوتے؟ ستے ہوئے، متردد آنکھوں والے، موت کی پرچھائیاں جن پر رقص کرتی ہوتی تھیں۔۔ اپنی موت کی نہیں تو کسی عزیز کی موت کے اندیشے کی۔ کہیں امید و بیم کی دھوپ چھاؤں کے درمیان، تو کہیں صرف اندھیروں کے درمیان۔۔
وہ نوجوان لڑکی اپنی خوبصورت آنکھوں میں ایک کربناک کیفیت لئے بڑے صبر کے ساتھ کرسی پر بیٹھی اپنا نام پکارے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بغل والی کرسی پر کسی نے رومال ڈال کر اپنی جگہ مختص کر دی تھی۔
’’میں یہاں بیٹھ جاؤں؟‘‘ اچانک وہ سوال، جو گرچہ نہایت ملائمیت اور شائستگی کے ساتھ کیا گیا تھا، اس کی سماعت پر ہتھوڑے کی طرح پڑا۔ چونکنے کے باوجود وہ خاموش رہی۔ اس کے ریشے ریشے میں ایک سُن ہو جانے والی کیفیت سمائی ہوئی تھی۔
سوال دوبارہ دوہرایا گیا۔ اس مرتبہ بڑی ہی نرمی کے ساتھ اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر۔ اس لمس کی ایک زبان تھی، گونگی زبان جواس لڑکی کے وجود میں اترنے میں کامیاب رہی تھی۔
اس نے آنکھیں اٹھائیں۔ سوال کرنے والی عورت عمر میں اس سے خاصی بڑی تھی۔ کوئی چالیس کے پیٹے میں۔ یا شاید کچھ اور زیادہ۔
”بیٹھ جائیے۔“ اس نے رسان سے کہا، ”یہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ آئیں گے تو اٹھ جائیےگا۔“
بڑی عورت رومال سرکا کر بیٹھ گئی۔ ہال ائرکنڈیشنڈ تھا لیکن بھیڑ کی وجہ سے اس کا تاثر کم ہو گیا تھا۔ پسینے اور دواؤں کی بو الگ رچ بس گئی تھی۔ عورت کو محسوس ہوتا تھا اس بڑے کمرے میں ایک اور بےنام مہک ہوا کرتی ہے جو سب سے الگ ہوتی ہے۔ اتنی عمر گذار لینے کے باوجود اس نے پہلے کبھی ایسی مہک نہیں سونگھی تھی۔ دبے پاؤں آتی موت کی مہک۔۔ آج بھی ایک اسٹریچر سرکا کر دیوار سے لگایا ہوا تھا۔ اس پر پڑا ایک شخص گویا اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ اس کے جسم میں کئی دوائیں داخل کی جا رہی تھیں۔ پاس ہی ایک عورت اسٹریچر کی پٹی پکڑے کھڑی تھی۔ دونوں بہت غریب، بےحد مسکین۔ یقیناً یہ مہک ان کے پاس سے آ رہی تھی۔ عورت جب جب اپنی باری پر یہاں آئی تھی، اس طرح کوئی نہ کوئی اسٹریچر اسے ضرور دکھائی دیا تھا۔ کبھی ادھر ادھر پہنچایا جاتا۔ کبھی دیوار سے لگا کر کھڑا کیا ہوا اور اسے ہر بار یہ خیال آیا تھا کہ ایسی حالت میں تو آرام سے مرنے دیا جاتا تو بہتر تھا۔ اتنی اذیت کے بدلے چند سانسیں دے کر کیا ملتا ہے؟ فضا میں موت کے قدموں کی چاپ یوں سنائی دیتی ہے جیسے کوئی تھکا ہوا دل آہستہ آہستہ کانوں میں آکر دھڑک رہا ہو۔
گھٹن ناقابل برداشت تھی۔ رومال رکھ جانے والا بھی ابھی نہیں آیا تھا۔ دوسرے کی سیٹ پر قابض ہونے کے خفیف سے احساسِ جرم کے ساتھ وہ عورت وہیں بیٹھی تھی۔ ایک عدم تحفظ کا احساس بھی تھا۔ ابھی وہ آ جائے گا اور اسے اٹھنا پڑے گا۔ جیسے اس کے عزیز کا نام پکارے جانے پر خود اسے بھی سیٹ چھوڑنی ہوگی۔ ہم سب اپنی اپنی طلبی کے منتظر ہیں۔ اس نے دلگرفتگی کے ساتھ سوچا۔۔۔ اندر اٹھتے سناٹے سے گھبرا کر وہ بغل میں بیٹھی لڑکی کی طرف مڑی۔
”کون بیمار ہے؟‘‘
’’میرے شوہر‘‘ اس نے مختصر جواب دیا۔
’’تمہارے شوہر؟‘‘ بڑی عورت نے حیرت سے دوہرایا، ’’ تمہاری شادی ہو چکی ہے؟ ذرا نہیں لگتا کہ تم شادی شدہ ہو۔ تمہارے شوہر بھی بالکل کم عمر ہوں گے۔‘‘اس کے لہجے میں دلی تاسف تھا۔ چچ چچ!
لڑکی نے ٹھنڈی سانس لی۔ سیاہ آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک لرزی، جیسے گھنے بادلوں کے پیچھے سے بجلی کی خفیف سی روشنی کا احساس۔ وہ خاموش رہی۔ یہاں ہر شخص بول رہا تھا لیکن کسی کو کسی کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی۔ دلوں میں سناٹا پسرا پڑا رہتا تھا بےکراں اور لامتناہی۔۔ بیک وقت موجود اس سناٹے اور شور کے درمیان ڈے کیئر وارڈ کے دروازے پر کھڑے باوردی گارڈ کی آواز مائک پر گونجتی۔ وہ لوگوں کے نام پکارتا تھا۔ کسی کے مریض کی کیموتھریپی مکمل ہو چکی ہوتی تو اس کے کاغذات لے کر اسے واپس لے جانا ہوتا۔ کسی کے لئے جگہ خالی ہوئی ہوتی تو مریض کو لے کر اندر پہونچانا ہوتا۔ کیمو کے درمیان بھی کبھی ساتھ آئے نگراں کی ضرورت پڑ جایا کرتی تھی۔ ذرا کی ذرا گارڈ کی کرخت آواز باقی آوازوں پر حاوی ہو جاتی، پل بھر کو سناٹا چھا جاتا۔ پھر انتظار کر رہے ہراساں لوگوں میں سے باری آجانے والا شخص ہڑبڑاکر اٹھتا۔
”روکیا کھاتُن۔۔۔روکیا کھاتُن۔۔۔“ مائک کھڑکھڑایا تھا۔
لمبی داڑھی اور ملگجے کرتے والا ایک نہایت تھکا تھکا سا شخص چوکنا ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حلئے بشرے سے آس پاس کے کسی دیہات سے آیا ہوا لگتا تھا۔ ویسے تو اس عظیم الشان شہر میں بھی اس طرح کے لوگوں کی کمی نہیں تھی۔ یہاں وہ بھی تھے جو سرسبز درختوں کے درمیان گھرے پرسکون، کشادہ اور خوبصورت بنگلوں میں رہتے تھے اور وہ بھی جو علی الصبح ٹھیلہ لے کر ان بنگلوں میں سبزیاں اور پھل پہنچایا کرتے تھے۔ وہ بھی جو کامن ویلتھ گیمز کے دوران عالیشان ہوٹلوں میں ٹھہرے تھے اور وہ بھی جنہوں نے سخت مشقت کر کے ان کے لئے شہر کو دلہن کی طرح سجایا تھا اور پھر نکال کر باہر کر دیے گئے تھے کہ رہ جاتے تو دلہن کے چہرے پر برص کے داغ کی طرح ابھر آتے۔ اس لئے کسی کی صورت دیکھ کر کوئی کیا سمجھ پاتا کہ وہ کہاں رہ رہا ہے۔۔ کسی گاؤں میں یا بڑے شہر کی جھونپڑ پٹی میں۔۔۔
اعلان کے بعد گارڈ نے چند لمحوں کا توقف کیا اور اس کے بعد باہر آ گیا۔ اس نے مائک اپنے اسٹول پر چھوڑ دیا تھا۔
’’روکیا کھاتُن کون ہے؟‘‘ بھیڑ کے درمیان گھس کر اس نے زور سے آواز لگائی ’’جلدی کیجئے، آپ لوگ پکارنے پر دھیان نہیں دیتے دوائی شروع ہونے میں دیر ہوتی ہے‘‘۔ گو اس کی آواز تیز تھی لیکن لہجہ نرم تھا۔ نرم اور ہمدرد۔
اسی ہسپتال کے دوسرے شعبوں میں وارڈ بوائے اور نرسیں اتنے نرم خُو نہیں تھے۔ ایک مرتبہ دواؤں اور پرہیز کی وضاحت کر دینے پر بات سمجھ میں نہ آئے اور مریض دوبارہ پوچھ بیٹھے تو خاصے ناراض ہوتے تھے۔ ’ارے کیا ہم صرف تمہارے لئے نوکری کر رہے ہیں؟ اتنے لوگ اور جو انتظار کر رہے ہیں، ان کا کیا؟‘ ایک مرتبہ ایک شخص کہہ بیٹھا ’میڈم اتنی دیر تک ڈانٹنے سے اچھا تھا کہ ایک بار اور سمجھا دیتیں۔۔‘ نرس نے اسے خشمگیں نظروں سے گھورا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ بےچارہ ایک ایک کو پکڑ پکڑ کر پوچھنے لگا کہ کتنی بار دوا کھانی ہے اور دوبارہ انجکشن لینے کب آنا ہے۔ بہت دیر بعد ایسا شخص مل سکا جو پڑھا لکھا بھی تھا اور مہربان صفت بھی۔ ویسے کئی پڑھے لکھے ایک نظر ڈال کر اس لئے بھی آگے بڑھ گئے تھے کہ کام کے دباؤ پر نسخہ لکھنے والے ڈاکٹروں کی گھسیٹی گئی جناتی تحریر پڑھ لینا سب کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ لیکن اس شعبے کے ڈے کیئر کا عملہ نہایت نرم خو اور خلیق تھا۔ سب جانتے تھے کہ یہاں جو آیا ہے، اس کا ٹکٹ کٹ چکا ہے۔۔ بس دو پاٹوں کے بیچ پس رہے چنے کے دانوں میں سے کوئی کوئی ہی بچ نکلے گا اور لوگ کہیں گے، ’ہاں بھائی جاکو راکھے سائیاں۔۔۔‘ سائیاں کو رکھنا ہو تو اس مرض میں مبتلا ہی کیوں کرتے۔
گود میں بڑی بڑی آنکھوں اور زرد چہرے والی تین چار برس کی لاغر بچی کو لئے وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا۔ ’’شاید ہمیں کو کہہ رہے ہیں۔ رقیہ خاتون کو بلا رہے ہیں۔‘‘
’’ہاں چلئے جلدی کیجئے‘‘ گارڈ نے بچی کی طرف پیار سے دیکھا۔۔۔ اس شخص نے تیز تیز چلتے ہوئے بچی کے ساتھ ہاتھ میں پکڑی فائل سنبھالی۔ ہڑ بڑائی ہوئی رفتار کے باوجود بچی کا منہ چوما۔ پھر وہ بدبدایا۔
’’پتہ نہیں کیسے کیسے نام بولتے ہیں گارڈ جی۔ ہماری سمجھ میں ایک بار بھی نہیں آیا۔ سسٹر ناراض ہوں گی، ٹائم کھوٹا ہو رہا ہے ان کا۔‘‘
’’کیسی چھوٹی سی، معصوم سی بچی ہے۔‘‘ بڑی عمر والی عورت پھر بولی۔
کچھ لوگ دکھ میں خاموش رہتے ہیں، کچھ بول بول کر جی ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عورت فطرتاً خاموش طبیعت تھی لیکن اب باتونی ہو گئی تھی۔ اسے لگتا تھا خاموش رہی تو کلیجہ پھٹ جائے گا۔
نوجوان لڑکی سر نیچا کئے بیٹھی تھی۔ اس نے پھر آنکھیں اوپر اٹھائیں، ’’میری بیٹی بھی اتنی ہی بڑی ہے‘‘اس کی آواز میں آنسوؤں کی کھنک تھی۔
’’ارے رے رے۔۔ کس کے پاس چھوڑ کر آئی ہو؟‘‘
’’ماں کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ دوسرے شہر میں رہتی ہیں۔ یہاں ان کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی تھی۔بچی رل رہی تھی۔‘‘
ایسا لگا جیسے اجنبی دیار میں، جہاں نفسی نفسی کا عالم تھا، ایک غیرمتوقع ہمدرد کی موجودگی نے لڑکی کے ضبط کا باندھ توڑ دیا تھا اور اس کی گونگی زبان بھی بول پڑی تھی۔
’’ایک اتنی ہی بڑی بچی کو میں نے آنکھ کے کینسر میں مبتلا دیکھا۔ درد سے سر پٹک رہی تھی۔ اس کی ماں ہاتھ مل مل کے رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ایسی بےبسی تھی کہ ایک نرس وہیں دھپ سے اس کے پاس بیٹھ گئی اور خود بھی رونے لگی۔‘‘ بڑی عورت نے کہا۔
’’بس کیجئے۔ یہاں اپنے دکھ کافی ہیں رونے کے لئے‘‘ نوجوان عورت کی آواز میں دبا دبا غصہ تھا۔
’’ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ ہمیں آپ کو یہ سب نہیں سنانا چاہئے تھا۔‘‘ بڑی عورت نے کہا اور خاموش ہو گئی۔
نوجوان لڑکی کو کچھ افسوس ہوا۔ آخر اس کا بھی تو کوئی نہ کوئی بیمار ہے۔ عمر میں اس سے بڑی بھی ہے۔اس سے اس طرح جھڑک کر نہیں بولنا چاہئے تھا۔ جو وہ بتا رہی تھی، اس طرح کے نظارے تو آنکھوں کے سامنے روز آتے رہتے ہیں۔ اس نے اپنی بدتمیزی کا کچھ تدارک کرنا چاہا۔ بڑی نرمی سے پوچھا: ”اور آپ کس لئے آئی ہیں؟ کون بیمار ہے آپ کا؟“
”میرا گیارہ سال کا بیٹا۔ کیمو چل رہی ہے اس کی۔۔“
”اوہ!“ نوجوان لڑکی اندر سے ہل گئی۔ ایک عورت کے لئے اولاد اس کے سہاگ سے بھی بڑی ہو جاتی ہے۔ اسے اپنی بچی یاد آئی، جسے وہ ماں کے پاس چھوڑ آئی تھی کہ شوہر کی بیماری کی وجہ سے وہ نظر انداز ہو رہی تھی۔ ہمہ وقت شوہر کے ساتھ لگے رہنے اور اداس و دل گرفتہ ہونے کے باوجود ایک لمحے کو بھی بچی ذہن سے اوجھل نہیں ہوتی تھی۔ ”آپ کے پتی؟“ اس نے بات جاری رکھنی چاہی۔
’’بچے کے ساتھ ہیں۔ ابھی باہر لے گئے ہیں۔ ہم لوگ سویرے سات بجے ہی آ گئے تھے۔ معلوم ہوا بارہ بجے کے بعد نمبر آئےگا۔‘‘
دونوں کے درمیان ایک گہری خاموشی نے پیر پسار دئے۔ ہال آوازوں سے گونجا کیا۔
پھر بڑی عورت نے ہی خاموشی توڑی، ’’وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ بڑی منت مرادوں کے بعد پیدا ہوا۔ دوا کر کر کے ہار گئے تھے۔ سارے پیر فقیر سنت اولیا بھی منا لئے۔ بالکل مایوس ہو چکے تھے، تبھی اچانک بارہ برس بعد اوپر والے نے ہماری گود بھر دی۔ مگر کیوں؟ کس لئے؟ شاید یہ جتانے کے لئے کہ اس کی مرضی نہ ہو تو اس سے ضد کر کے کچھ نہیں مانگنا چاہئے۔ بےاولاد ہونے کا دکھ تو اس دکھ سے بہتر تھا۔‘‘
نوجوان عورت پھر اندر سے ہل گئی۔ ایک اولاد، وہ بھی شادی کے بارہ برس بعد اللہ آمین کا بچہ۔۔
بڑی عورت خاموش نہیں ہوئی تھی۔ اس کی بات جاری تھی۔ ’’ہم سخت وجیٹیرین تھے۔ انڈا تک ہمارے گھر نہیں آتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا لڑکے کو پروٹین زیادہ دینے ہیں۔ ہم نے اسے نان ویج کھلانا شروع کیا۔ ایک آدھ بار ہوٹل سے لائے۔ لیکن پھر سوچا ڈاکٹر نے انفکشن سے خبردار کیا ہے۔ اس لئے ہم نے گھر ہی میں بنانا شروع کر دیا۔ اولاد کے لئے ہم نے دھرم اٹھا کے طاق پر رکھ دیا۔ اب ہمارے گھر کے اندر انڈا مرغا سب بن رہا ہے۔ کوکری کلاس جوائین کر کے یہ سب بنانا سیکھا۔ طرح طرح کی ڈشیں بناتے ہیں۔ اپنے ہاتھ سے تھالی پروستے ہیں۔ ہاتھ سے نوالہ بنا کر منہ میں دیتے ہیں۔ شوق سے کھاتا ہے۔ جتنے دن بھی اس کی سیوا کا سکھ پا لیں۔‘‘ اس کی آواز میں اب کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس کا غم شدت کی اس انتہا کو پہنچ گیا تھا، جہاں سب کچھ شونیہ (صِفر) میں گم ہو جاتا ہے۔
کھرکھراتی ہوئی آواز میں تبھی اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا ’’وہ رہے باپ بیٹا۔ سوا بارہ بج بھی رہے ہیں۔ اب نمبر ضرور آ جائے گا۔ میرا بچہ، میرا غریب معصوم بچہ۔۔ ہر تین ہفتہ پر تکلیف اٹھاتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں ففٹی ففٹی چانس ہے۔‘‘
نوجوان عورت نے اس طرف دیکھا۔ دیکھنے میں ذرا نہیں لگ رہا تھا کہ بچہ بلڈ کینسر کا مریض ہے۔ گورا، چٹا، مزے کے ڈیل ڈول والا۔ بس آنکھوں میں زردی کھنڈی ہوئی تھی اور سر گھٹا ہوا تھا۔ کیمو تھیریپی کے ردعمل سے بال گر جانے پر بہت سی عورتوں تک نے سر منڈوا کر اسکارف باندھے ہوئے تھے۔
نوجوان عورت نے گلے میں کچھ پھنستا ہوا محسوس کیا اور پلکیں جھپکا کر دوسری طرف دیکھنے لگی۔
اسی وقت مائک کھڑکھڑایا اور گارڈ نے کچھ کاغذات پر نظر دوڑاتے ہوئے آواز لگائی ’’اکھیل، اکیل۔۔۔ اوہ اکل۔۔۔ اکھیل کے گھر والے آ جائیں۔‘‘
بڑی عورت بےاختیار اٹھ کھڑی ہوئی ’’آ جاؤ بیٹا تمہارا نمبر آ گیا ہے۔‘‘
نوجوان عورت بھی اسی اضطراری کیفیت کے تحت اٹھ گئی تھی۔
’’نہیں یہ عقیل کے لئے کہہ رہا ہے، میرے شوہر کے لئے۔۔ وہ بیڈ پر ہیں۔ دوا چڑھ رہی ہے۔ کچھ چاہئے ہوگا۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔‘‘
گارڈ نے اس مرتبہ ہکلاہٹ پر قابو پاکر نام ذرا زور دے کر دوہرایا۔۔۔’’اکِھیل کے ساتھ والے آ جائیں۔۔۔‘‘
’’نہیں نہیں ہمارا نمبر آ گیا ہے۔‘‘ بڑی عورت تیزی سے چلتی ہوئی بولی۔
اکھیل پانڈے یا عقیل احمد۔۔۔؟ دونوں خواتین تیز تیز قدموں سے گارڈ کی طرف بڑھ رہی تھیں۔
آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز دہلی کے بی آر امبیدکر کینسر انسٹیٹیوٹ کے ڈے کئیر سیکشن میں ہمہ ہمی جاری تھی۔۔




