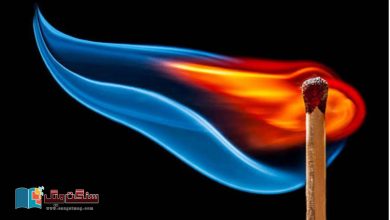آٹھویں مرتبہ ہم سب مسافروں نے لاری کو دھکا دیا اور دھکیلتے ہوئے خاصی دور تک چلے گئے، لیکن انجن گنگنایا تک نہیں۔ ڈرائیور گردن ہلاتا ہوا اتر پڑا۔ کنڈکٹر سڑک کے کنارے ایک درخت کی جڑ پر بیٹھ کر بیڑی سلگانے لگا۔ مسافروں کی نظریں گالیاں دینے لگیں اور ہونٹ بڑبڑانے لگے۔ میں بھی سڑک کے کنارے سوچتے ہوئے دوسرے پیڑ کی جڑ پر بیٹھ کر سگریٹ بنانے لگا۔ ایک بار نگاہ اٹھی تو سامنے دور درختوں کی چوٹیوں پر مسجد کے مینار کھڑے تھے۔ میں ابھی سگریٹ سلگا ہی رہا تھا کہ ایک مضبوط کھردرے دیہاتی ہاتھ نے میری چٹکیوں سے آدھی جلی ہوئی تیلی نکال لی۔ میں اس کی بے تکلفی پر ناگواری کے ساتھ چونک پڑا مگر وہ اطمینان سے اپنی بیڑی جلا رہا تھا۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھ کر بیڑی پینے لگا یا بیڑی کھانے لگا۔
’’یہ کون گاؤں ہے؟‘‘ میں نے میناروں کی طرف اشارہ کر کے پوچھا۔
’’یو۔۔۔ یو بھسول ہے۔‘‘
بھسول کا نام سنتے ہی مجھے اپنی شادی یاد آ گئی۔ میں اندر سلام کرنے جا رہا تھا کہ ایک بزرگ نے ٹوک کر روک دیا۔ وہ کلاسیکی کاٹ کی بانات کی اچکن اور پورے پائنچے کا پاجامہ اور فر کی ٹوپی پہنے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں نے سر اٹھا کر ان کی سفید پوری مونچھیں اور حکومت سے سینچی ہوئی آنکھیں دیکھیں۔ انہوں نے سامنے کھڑے ہوئے خدمتگار کے ہاتھ سے پوالوں کی بدھیاں لے لیں اور مجھے پہنانے لگے۔ میں نے بل کھا کر اپنی بنارسی پوت کی جھلملاتی ہوئی شیروانی کی طرف اشارہ کر کے تلخی سے کہا، ’’کیا یہ کافی نہیں تھی؟‘‘ وہ میری بات پی گئے۔ بدھیاں برابر کیں پھر میرے ننگے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا کر کہا، ’’اب تشریف لے جائیے۔‘‘ میں نے ڈیوڑھی پر کسی سے پوچھا کہ ’’یہ کون بزرگ تھے۔‘‘ بتایا گیا کہ یہ بھسول کے قاضی انعام حسین ہیں۔
بھسول کے قاضی انعام حسین، جن کی حکومت اور دولت کے افسانے میں اپنے گھر میں سن چکا تھا۔ میرے بزرگوں سے ان کے جو مراسم تھے، مجھے معلوم تھے۔ میں اپنی گستاخ نگاہوں پر شرمندہ تھا۔ میں نے اندر سے آ کر کئی بار موقع ڈھونڈ کر ان کی چھوٹی موٹی خدمتیں انجام دیں۔ جب میں چلنے لگا تو انہوں نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا، مجھے بھسول آنے کی دعوت دی اور کہا کہ اس رشتے سے پہلے بھی تم میرے بہت کچھ تھے لیکن اب تو داماد بھی ہو گئے ہو۔ اس قسم کے رسمی جملے سبھی کہتے ہیں لیکن اس وقت ان کے لہجے میں خلوص کی ایسی گرمی تھی کہ کسی نے یہ جملے میرے دل پر لکھ دیے۔
میں تھوڑی دیر کھڑا بگڑی ’’بس‘‘ کو دیکھتا رہا۔ پھر اپنا بیگ جھلاتا ہوا جتے ہوئے کھیتوں میں اٹھلاتی ہوئی پگڈنڈی پر چلنے لگا۔ سامنے وہ شاندار مسجد کھڑی تھی، جسے قاضی انعام حسین نے اپنی جوانی میں بنوایا تھا۔ مسجد کے سامنے میدان کے دونوں طرف ٹوٹے پھوٹے مکان کا سلسلہ تھا، جن میں شاید کبھی بھسول کے جانور رہتے ہوں گے۔ ڈیوڑھی کے بالکل سامنے دو اونچے آم کے درخت ٹریفک سپاہی کی طرح چھتری لگائے کھڑے تھے۔ ان کے تنے جل گئے تھے، جگہ جگہ مٹی بھری تھی۔ ڈیوڑھی کے دونوں طرف عمارتوں کے بجائے عمارتوں کا ملبہ پڑا تھا۔ دن کے تین بجے تھے۔ وہاں اس وقت نہ کوئی آدمی تھا نہ آدم زاد کہ ڈیوڑھی سے قاضی صاحب نکلے، لمبے قد کے جھکے ہوئے، ڈوریے کی قمیص، میلا پاجامہ اور موٹر ٹائرکے تلووں کا پرانا پمپ پہنے ہوئے، ماتھے پر ہتھیلی کا چھجہ بنائے مجھے گھور رہے تھے۔ میں نے سلام کیا۔ جواب دینے کے بجائے وہ میرے قریب آئے اور جیسے یک دم کھل گئے، میرے ہاتھ سے میرا بیگ چھین لیا اور میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ڈیوڑھی میں گھس گئے۔
ہم اس چکر دار ڈیوڑھی سے گزر رہے تھے جس کی اندھیری چھت کمان کی طرح جھکی ہوئی تھی۔ دھنیوں کو گھنے ہوئے بدصورت شہتیر روکے ہوئے تھے۔
وہ ڈیوڑھی ہی سے چلائے، ’’ارے سنتی ہو۔۔۔ دیکھو تو کون آیا ہے۔ میں نے کہا اگر صندوق وندوق کھولے بیٹھی ہو تو بند کر لو جلدی سے۔‘‘
لیکن دادی تو سامنے ہی کھڑی تھیں، دھلے ہوئے گھڑوں کی گھڑونچی کے پاس دادا ان کو دیکھ کر سٹپٹا گئے۔ وہ بھی شرمندہ سی کھڑی تھیں۔ پھر انہوں نے لپک کر گھر کی الگنی پر پڑی مارکین کی دھلی چادر گھسیٹ لی اور دوپٹہ کی طرح اوڑھ لی۔ چادر کے ایک سرے کو اتنا لمبا کر دیا کہ کرتے کے دامن میں لگا دوسرے کپڑے کا چمکتا پیوند چھپ جائے۔
اس اہتمام کے بعد وہ میرے پاس آئیں، کانپتے ہاتھوں سے بلائیں لیں۔ سکھ اور دکھ کی گنگا جمنی آواز میں دعائیں دیں۔ دادی کانوں سے میری بات سن رہی تھیں، لیکن ہاتھوں سے، جن کی جھریاں بھری کھال جھول گئی تھی، دالان کے اکلوتے ثابت پلنگ کو صاف کر رہی تھیں۔ جس پر میلے کپڑے، کتھے چونے کی کلھیاں اور پان کی ڈلیاں ڈھیر تھیں اور آنکھوں سے کچھ اور سوچ رہی تھیں۔ مجھے پلنگ پر بٹھا کر دوسرے جھنگا پلنگ کے نیچے سے وہ پنکھا اٹھالائیں، جس کے چاروں طرف کالے کپڑے کی گوٹ لگی تھی اور کھڑی ہوئی میرے اس وقت تک جھلتی رہیں، جب تک میں نے چھین نہ لیا۔ پھر وہ باورچی خانے میں چلی گئیں۔
وہ ایک تین دروں کا دالان تھا۔ بیچ میں مٹی کا چولہا بنا تھا۔ المونیم کی چند میلی پتیلیاں، کچھ پیپے، کچھ ڈبے، کچھ شیشے بوتل اور دو چار اسی قسم کی چھوٹی موٹی چیزوں کے علاوہ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ وہ میری طرف پیٹھ کئے چولہے کے سامنے بیٹھی تھیں۔ دادا نے کونے میں کھڑے ہوئے پرانے حقہ سے بے رنگ چلم اتاری اور باورچی خانہ میں گھس گئے۔ میں ان دونوں کی گھن گھن کرتی سرگوشیاں سنتا رہا۔ دادا کئی بار جلدی جلدی باہر گئے اور آئے۔ میں نے اپنی شیروانی اتاری ادھر ادھر دیکھ چھ دروازوں والے کمرے کے کواڑ پر ٹانگ دی۔ کیواڑ کو دیمک چاٹ گئی تھی۔ ایک جگہ لوہے کی پتی لگی تھی۔ لیکن بیچوں بیچ گول دائرے میں ہاتھی دانت کا کام، کتھے اور تیل کے دھبوں میں جگمگا رہا تھا۔ بیگ کھول کر میں نے چپل نکالے اور جب تک میں دوڑوں دوڑوں، دادا گھڑونچی پر سے گھڑا اٹھا کر اس لمبے چوڑے کمرے میں رکھ آئے جس میں ایک بھی کیواڑ نہ تھا، صرف گھیرے لگے کھڑے تھے۔ جب میں نہانے گیا تو دادا الو نیم کا لوٹا میرے ہاتھ میں پکڑا کر مجرم کی طرح بولے، ’’تم بیٹے اطمینان سے نہاؤ۔۔۔ ادھر کوئی نہیں آئے گا۔ پردے تو میں ڈال دوں لیکن اندھیرا ہوتے ہی چمگادڑ گھس آئے گی اور تم کو دق کرے گی۔‘‘
میں گھڑے کو ایک کونے میں اٹھا لے گیا۔ وہاں دیوار سے لگا، اچھی خاصی سینی کے برابر پیتل کا گھنٹہ کھڑا تھا۔ میں نے جھک کر دیکھا گھنٹے میں مونگریوں کی مار سے داغ پڑ گئے تھے۔ دو انگل کا حاشیہ چھوڑ کر جو سوراخ تھا، اس میں سوت کی کالی رسی بندھی تھی۔ اس سوراخ کے برابر ایک بڑا سا چاند تھا، اس کے اوپر سات پہل کا ستارہ تھا۔ میں نے تولیہ کے کونے سے جھاڑ کر دیکھا تو وہ چاند تارا بھسول اسٹیٹ کا مونو گرام تھا۔ عربی رسم الخط میں ’’قاضی انعام حسین آف بھسول اسٹیٹ اودھ‘‘ کھدا ہوا تھا۔ یہی وہ گھنٹہ تھا جو بھسول کی ڈیوڑھی پر اعلانِ ریاست کے طور پر تقریباً ایک صدی سے بجتا چلا آ رہا تھا۔ میں نے اسے روشنی میں دیکھنے کے لئے اٹھانا چاہا لیکن ایک ہاتھ سے نہ اٹھا سکا۔ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر دیکھتا رہا۔ میں دیر تک نہاتا رہا، جب باہر نکلا تو آنگن میں قاضی انعام حسین پلنگ بچھا رہے تھے۔
قاضی انعام حسین، جن کی گدی نشینی ہوئی تھی، جن کے لئے بندوقوں کا لائسنس لینا ضروری نہیں تھا، جنہیں ہر عدالت طلب نہیں کر سکتی تھی، دونوں ہاتھوں پر خدمتگاروں کی طرح طباق اٹھائے ہوئے آئے جس میں الگ الگ رنگوں کی دو پیالیاں ’لب سوز‘ لب بند چائے سے لبریز رکھی تھیں۔ ایک بڑی سی پلیٹ میں دو ابلے ہوئے انڈے کاٹ کر پھیلا دیے گئے تھے۔
شروع اکتوبر کی خوشگوار ہوا کے ریشمی جھونکوں میں ہم لوگ بیٹھے نمک پڑی ہوئی چائے کی چسکیاں لے رہے تھے کہ دروازے پر کسی بوڑھی آواز نے ہانک لگائی، ’’مالک۔‘‘
’’کون؟‘‘
’’مہتر ہے آپ کا۔۔۔ صاحب جی کا بلابے آئے ہے۔‘‘
دادا نے گھبرا کر احتیاط سے اپنی پیالی طباق میں رکھی اور جوتے پہنتے ہوئے باہر چلے گئے، اپنے بھلے دنوں میں تو اس طرح شاید وہ کمشنر کے آنے کی خبر سن کر بھی نہ نکلے ہوں گے۔
میں ایک لمبی ٹہل لگا کر جب واپس آیا تو ڈیوڑھی میں مٹی کے تیل کی ڈبیا جل رہی تھی۔ دادا باورچی خانے میں بیٹھے چولہے کی روشنی میں لالٹین کی چمنی جوڑ رہے تھے۔ میں ڈیوڑھی سے ڈبیا اٹھا لایا اور اصرار کر کے ان سے چمنی لے کر جوڑنے لگا۔ ہاتھ بھر لمبی لالٹین کی تیز گلابی روشنی میں ہم لوگ دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ دادا میرے بزرگوں سے اپنے تعلقات بتاتے رہے۔ اپنی جوانی کے قصے سناتے رہے۔ کوئی آدھی رات کے قریب دادی نے زمین پر چٹائی بچھائی اور دسترخوان لگایا۔ بہت سی ان میل بے جوڑ اصلی چینی کی پلیٹوں میں بہت سی قسموں کا کھانا چنا۔ شاید میں نے آج تک اتنا نفیس کھانا نہیں کھایا۔
صبح میں دیر سے اٹھا۔۔۔ یہاں سے وہاں تک پلنگ پر ناشتہ چنا ہوا تھا۔ دیکھتے ہی میں سمجھ گیا کہ دادی نے رات بھر ناشتہ پکایا ہے۔ جب میں اپنا جوتا پہننے لگا تو رات کی طرح اس وقت بھی دادی نے مجھے آنسو بھری آواز سے روکا۔ میں معافی مانگتا رہا۔ دادی خاموش کھڑی رہیں، جب میں شیروانی پہن چکا، دروازے پر یکہ آ گیا، تب دادی نے کانپتے ہاتھوں سے میرے بازو پر امام ضامن باندھا، ان کے چہرے پر چونا پتا ہوا تھا۔ آنکھیں آنسوؤں سے چھلک رہی تھیں۔ انہوں نے رندھی ہوئی آواز میں کہا، ’’یہ اکاون روپے تمہاری مٹھائی کے ہیں اور دس کرائے کے۔‘‘
’’ارے۔۔۔ ارے دادی۔۔۔ آپ کیا کر رہی ہیں۔‘‘ اپنی جیب میں جاتے ہوئے روپوں کو میں نے پکڑ لیا۔
’’چپ رہو تم۔۔۔ تمہاری دادی سے اچھے تو ایسے ویسے لوگ ہیں۔۔۔ جو جس کا حق ہوتا ہے، وہ دے تو دیتے ہیں۔۔۔ غضب خدا کا، تم زندگی میں پہلی بار میرے گھر آؤ اور میں تم کو جوڑے کے نام پر ایک چٹ بھی نہ دے سکوں۔۔۔ میں۔۔۔ بھیا۔۔۔ تیری دادی تو فقیر ہو گئی۔۔۔ بھکارن ہو گئی۔‘‘
معلوم نہیں کہاں کہاں کا زخم کھل گیا تھا۔ وہ دھاروں دھار رو رہی تھیں، دادا میری طرف پشت کیے کھڑے تھے اور جلدی جلدی حقہ پی رہے تھے۔
مجھے رخصت کرنے دادی ڈیوڑھی تک آئیں لیکن منہ سے کچھ نہ بولیں۔ میری پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر اور گردن ہلا کر رخصت کر دیا۔
دادا قاضی انعام حسین تعلقدار بھسول تھوڑی دیر تک میرے یکہ کے ساتھ چلتے رہے، لیکن نہ مجھ سے نگاہ ملائی نہ مجھ سے خدا حافظ کہا۔ ایک بار نگاہ اٹھا کر دیکھا اور میرے سلام کے جواب میں گردن ہلا دی۔
سدھولی، جہاں سے سیتا پور کے لیے مجھے بس ملتی، ابھی دور تھا۔ میں اپنے خیالوں میں ڈوبا ہوا تھا کہ میرے یکہ کو سڑک پر کھڑی ہوئی سواری نے روک لیا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میرا یکہ والا ہاتھ جوڑے مجھ سے کہہ رہا تھا، ’’۔۔۔ میاں۔۔۔ اِلی شاہ جی بھسول کے ساہوکار ہیں، ان کے یکہ کا بم ٹوٹ گوا ہے، آپ برا نہ مانو تو الی بیٹھ جائیں۔‘‘
میری اجازت پا کر اس نے شاہ جی کو آواز دی۔ شاہ جی ریشمی کرتا اور مہین دھوتی پہنے آئے اور میرے برابر بیٹھ گئے اور یکے والے نے میرے اور ان کے سامنے ’پیتل گھنٹہ‘ دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر رکھ دیا۔ گھنٹے کے پیٹ میں مونگری کی چوٹ کا داغ بنا تھا۔ دو انگل کے حاشیے پر سوراخ میں سوت کی رسی پڑی تھی۔ اس کے سامنے ’قاضی انعام حسن آف بھسول اسٹیٹ اودھ‘ کا چاند اور ستارے کا مونو گرام بنا ہوا تھا، میں اسے دیکھ رہا تھا اور شاہ جی مجھے دیکھ رہے تھے اور یکے والا ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ یکے والے سے رہا نہ گیا، اس نے پوچھ ہی لیا، ’’کا شاہ جی گھنٹہ بھی خرید لایو؟‘‘
’’ہاں! کل شام کا معلوم نائی، کا وقت پڑا ہے میاں پر کہ گھنٹہ دئے دیہن بلائے کے۔ ایی۔۔۔‘‘
’’ہاں وقت وقت کی بات ہے۔۔۔ شاہ جی نا ہیں تو ای گھنٹہ۔۔۔‘‘
’’اے گھوڑے کی دم! راستا دیکھ کے چل۔۔۔‘‘ یہ کہہ کر اس نے چابک جھاڑا۔
میں۔۔۔ میاں کا برا وقت۔۔۔ چوروں کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے معلوم ہوا کہ یہ چابک گھوڑے کے نہیں، میری پیٹھ پر پڑا ہے۔
( ’’پیتل کا گھنٹہ‘‘ کہانی کا تعلق قاضی انعام حسین آف بھسول اسٹیٹ اودھ سے ہے۔ آزادی سے پہلے بھسول اسٹیٹ کی جاہ وحشمت اور شان و شوکت قرب و جوار میں مشہور تھی۔ اس اسٹیٹ کے مالکوں کی گدی نشینی ہوتی تھی۔ جن کی عالیشان حویلی تھی، باغات تھے، ہاتھی گھوڑے تھے سپاہی اور نوکر چاکر تھے۔ انھوں نے ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ ان کی زمینداری کئی گاؤں میں تھی، ان کے یہاں کچہری لگتی تھی اور وہ خود مقدمہ کا فیصلہ کرتے تھے۔ ارباب اِقتدار میں ان کی بڑی عزت تھی لیکن آزادی کے بعد خاتمہ زمینداری اور تعلقداری کا اعلان ہوا تو دھیرے دھیرے ان کی خوشحالی بد حالی میں تبدیل ہوتی گئی۔ عالیشان عمارت کھنڈر میں تبدیل ہوگئی۔ جہاں اہل کاروں اور رشتہ داروں کا ہجوم رہتا تھا اب وہاں آدم نہ آدم زاد فقط دو نفر بوڑھے قاضی انعام حسین اور ان کی بوڑھی بیوی کسمپرسی کے عالم میں زندگی کے باقی دن کاٹ رہے ہیں۔۔ ایک زمانہ تھا جب کہ عزیز و اقارب کی خاطر داری بڑے اہتمام سے ہوتی تھی۔ اَن گنت نوکر چاکر، غریب، یتیم، مسکین دولت خانہ سے پرورش پاتے تھے۔ اب صورت حال یہ ہے کہ مقرب مہمانوں کی میزبانی گراں گزرتی ہے۔ آمدنی اس قدر قلیل ہے کہ میزبانی کے اہتمام میں گھر کے اثاثے بیچنے پڑتے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ برسوں بعد جب ان کا داماد ان کے گھر آتا ہے تو اس کی آئو بھگت میں ان کا پیتل کا وہ گھنٹہ بِک جاتا ہے، جو ان کی ڈیوڑھی پر اعلان ریاست کے طور پر تقریباََ ایک صدی سے بجتا چلا آرہا تھا۔ یہ المیہ اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔)